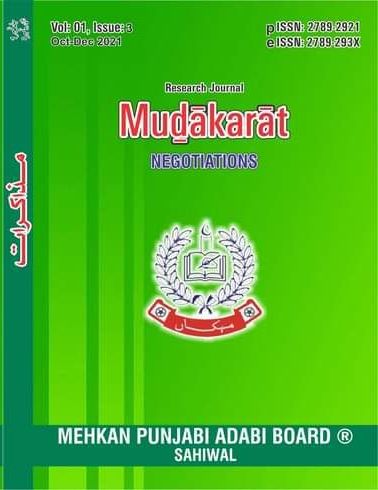1
2
2021
1682060054107_1845
16-24
http://journals.mehkaa.com/index.php/negotiations/article/download/16/9
http://journals.mehkaa.com/index.php/negotiations/article/view/16
Language Importance Language Types Mother Tongue Regional Language Official Language Sign Language
زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں کےذریعے سےایک دوسرے سے رابطہ یا معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کئی ایک زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے وجود سے انکار ممکن نہیں لیکن کچھ زبانیں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور کچھ زبانیں بہت تیزی سے ناپید بھی ہورہی ہیں۔ کیونکہ مختلف زبانوں کی تخلیق اور ان کی ترقی کا دارومدار بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کسی زبان کو ترقی دینے کے سلسلے میں اْس زبان سے کس حد تک مخلص ہیں۔ جس زبان کو ہم ترقی دے رہے ہیں صرف وہی زبان ہمارے سامنے باقی رہ جائے گی۔ مختلف زبانوں کی تخلیق و ترقی کا تجزیہ لسانیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر زبان معاشرے کی ضرورت اور ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ چیکوسلواکیہ کی ایک مثل ہے کہ ایک نئی زبان سیکھو اور ایک نئی روح حاصل کرو:
Learn a new language and get a new soul
یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی زبان کا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہے۔ اگرچہ زیادہ زبانیں جاننا بذات خود انسانی ارتقاء کے لیے ضروری نہیں لیکن انسانی ارتقاء کا تجربہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہوں۔پروفیسر خلیل صدیقی اس حوالے سے لکھتے ہیں: "زبان چند ایسے مفردات اور مرکبات کا مجموعہ ہے جو مختلف انسانی جماعتوں میں بطور مقررہ اشارات کے کام دیتے ہوں یا ایسے تلفظ، اشارات جو انسان کے منہ اور زبان سے مختلف رنگوں میں خارج ہوتے ہوں اور جن کے کچھ نہ کچھ معنی اور تغیرات ہوں"1
زبان ایک مربوط نظام کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے اورجس قدر کسی زبان کا استعمال روزبروزبڑھتا چلا جاتا ہے وہ زبان اسی قدر مضبوط اور ترقی پذیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ شروع دن سے جو زبان بچے کے ساتھ بولی جاتی ہے وہ اس کی مادری زبان بن جاتی ہے۔مادری زبان چونکہ گھر کے اندر بولی اور سمجھی جاتی ہے جو کہ بچے کو والدین کی طرف سے ملتی ہے لیکن بعض اوقات گھر کے باہر عام طور پرمعاشرے میں کسی دوسری زبان کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو دوسری زبان کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر خیبرپختونخواہ کا اگر کوئی باشندہ سندھ کے کسی علاقے میں رہ رہا ہے تو وہ پشتو کے ساتھ ساتھ سندھی بھی بول سکے گا۔ اگرچہ سندھی اس کی مادری زبان نہیں ہے۔
حکومت عوام کے ساتھ اپنے کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے جس زبان کا استعمال کرتی ہے اسے سرکاری زبان کہتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری زبان انگریزی استعمال کی جار ہی ہے۔ دفتری زبان سے مراد وہ زبان ہے جسے حکومت نے دفتری استعمال کے لیے رائج کر رکھا ہو۔ قومی زبان سے مراد وہ زبان ہے جو کسی ایک خطے یا علاقے میں بولی جائے اور اس خطے کے تمام لوگ اس زبان کو سمجھتے ہوں۔ بے شک ان کی اپنی علاقائی زبانیں الگ الگ ہوں لیکن جب ایک علاقے کا باشندہ دوسرے علاقے میں جائے تو اپنی بات سمجھانے کے لیے جس زبان کا سہارا لے وہ زبان دوسرے خطے کے لوگ بھی سمجھتے ہوں۔ رابطے کی زبان دو خطوں /ملکوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے وہ رابطے کی زبان کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں رابطے کی زبان عام طور پر انگریزی مراد لی جاتی ہے۔
زبان کے بولنے اور اس کے تحریر کرنے میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی زبان بولتے ہیں تو اس میں اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا اور اتنی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن جب ہم زبان کو تحریری شکل میں لکھتے ہیں تو ہمیں کچھ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم جو بات بول جاتے ہیں وہ لکھ نہیں سکے۔
جو لوگ زبان بول نہیں سکتے انھوں نے اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کچھ اشارے وضع کر رکھے ہیں جن سے وہ اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے میں مدد لیتے ہیں۔ اس زبان کو اشاروں کی زبان کہتے ہیں اور یہ کسی بحث کے زمرے میں نہیں آتی صرف بات سمجھنے یا سمجھانے کے لیے استعمال ہوسکتی ہے۔بعض اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے مخصوص علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو صرف کوئی خفیہ بات سمجھنے یا سمجھانے کے لیے علامت وضع کی جاتی ہے۔ علامتوں کی اس زبان پربھی کوئی بحث نہیں کی جاسکتی۔ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ زبان کے ارتقائی مراحل کے سلسلے میں مندرجہ بالا زبانوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبان کو اگر خاص خاص زمروں میں تقسیم کر کے دیکھا جائے تو ہر ایک زمرے کی اہمیت کس قدر واضح ہے کہ جن کے باہم ملاپ سے زبان کا یہ ڈھانچہ مکمل ہونے کے بعد اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔
زبان عطیہ خداوندی ہے اس کا آغاز کب اور کیوں ہوا اس سوال کا جواب ہمارے پاس صرف یہی ہو سکتاہے کہ جب سے حضرت انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اس وقت سے زبان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ انجیل میں حضرت آدم اور شیطان کی گفتگو کا جس طرح حوالہ دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی انسانی تاریخ ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق برھما نے آریہ تہذیب کو لکھنے کا علم دیا۔ 2 جس کے مطابق:"تورات میں زبانوں کے اختلاف کی یہ توجیہ کی گئی ہے کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اس کی پاداش میں اس کی نسل میں زبان کے اختلاف پیدا کر دیئے گئے"3
افلاطون نے "کرے تائی لس" (Kratylos) میں زبان کے مختلف مسائل پر اظہار خیال کیا۔ اس نے پہلی بار الفاظ اور ان کے معنی کے تعلق سے مباحث پیش کیے۔ یونانی اور رومن مفکرین کے زبان کے حوالے سے فلسفیانہ خیال یورپ میں بھی لسانیات کی روایت کے ابتدائی نقوش قرار دیے جا سکتے ہیں۔
لسانیات کی روایت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں زبانوں کے مطالعے کے محرکات مختلف نوعیت کے حامل رہے ہیں۔ قدیم ہند میں لسانی مطالعے کے محرکات مذہبی نوعیت کے تھے۔ اس طرح مسلمانوں نے قومی زبان کی صرف و نحو کی تدوین اس نقطہ نظر سے کی کہ قرآن مجید کی زبان جو غیر مسلمانوں کے لیے اجنبی تھی۔ اس لیے انہیں قرآن مجید کی قرأت اور تفہیم میں مشکلات ہوتی تھیں اس لیے مسلمانوں نے لغات کے مرتب کرنے پر توجہ دی۔ اس طرح سیاسی اور مذہبی محرکات کے زیر اثر لسانی مطالعے ہوئے۔محی الدین قادری زور نے لسانیات کو زبان کی پیدائش ،ارتقا اورموت سے متعلق ایک علم قراردیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:"لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان کی ماہیت،تشکیل، ارتقا، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے" 4
ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اپنے اسی بیان میں پاننی کو سنسکرت کا پہلا قواعد دان قرار دیا ہے۔ جب کہ یہ درست نہیں ہے۔ پاننی نے "اشٹ ادھیائے"میں اپنے چونسٹھ پیش روؤں کا ذکر کیا ہے اور اس امر کا حوالہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے بھی دیا ہے وہ لکھتے ہیں:"پاننی نے اپنی اس قواعد میں کم از کم چونسٹھ پیش روؤں کا ذکر کیا ہے"5
ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے پہلے پاننی کو سنسکرت کا اولین قواعد دان قرار دیا ہے اور پھر اس کے پیش روؤں کا ذکر بھی کیا ہے جس سے تضاد پیدا ہوتا ہے۔ پاننی کے عہد کا قطعی تعین نہیں کا سکا۔ گولڈ اسٹکر اور روبنس نے پاننی کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح قرار دیا ہے۔ ہیم چند رائے پانچویں صدی ق۔م اور بلوفیلڈ نے ۳۵۰ ق۔م تا ۵۲۰ ق۔م کا درمیانی عہد پاننی کے لیے مخصوص کیا ہے اور ہندو کلاسیکل ڈکشنری میں یہ چوتھی صدی قبل مسیح ہے۔
لسانیات کی تاریخ میں زبان کے آغاز کے مسائل خاصی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ عربی علماء نے بھی ان مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ ابوالحسن اشعری نے دسویں صدی عیسوی کے اوائل میں آغاز زبان کا الہیاتی نظریہ پیش کیا اور بعد میں سعید ابن جہیر، جلال الدین سیوطی، ابن حاجب، ابن زید اور ابن فارس و دیگر علماء نے بھی آغاز زبان کے الہیاتی نظریے کو اپنے اپنے طور پر پیش کیا۔ ان کے خیال کے مطابق:"الفاظ کی وضع ایجاد و توقیت سے ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو انہیں گفتگو کے لیے الفاظ بھی بتائے۔ پھر جب وہ اس خاکدان عالم میں آئے تو حسب ضرورت الفاظ کی وحی بھی ان کی جانب ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مجموعہ الفاظ نے ایک زبان کی صورت اختیار کر لی" 6
یورپ میں لسانی مطالعے کی قدیم روایت کی نوعیت بڑی حد تک فلسفیانہ رہی ہے جس کا تعلق یونان اور اسکندریہ سے ہے کیونکہ یونان کے فلسفیوں نے زبان کی ماہیت کا فلسفیانہ انداز سے مطالعہ اور تجزیہ کیاہے۔ یونان کی لسانی روایات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یونانی ماہرین لسانیات نے ارسطو اور اس کے مقلدین کے لسانی نظریات سے رہنمائی حاصل کی تھی اور یونانی زبان کی گرائمر کی بنیاد رکھی۔ انھوں نے ارسطو کے بتائے ہوئے تین اجزائے کلام یعنی مبتدا، خبر اور کلمات ربط میں چوتھے کا اضافہ کیا اور اسے تشکیر (Articles)کی اصطلاح سے موسوم کیا۔ انھوں نے بنیادی کلمے سے انحراف اور مستشقات کو بھی محسوس کیا۔ انھوں نے فعل کے صیغے اور طور کے فرق و امتیازکو بھی پہچانا اور فعل کی لسانیاتی توضیح کی اور یہ بھی دریافت کیا کہ بعض کلمے معنوں کے لحاظ سے اسم اور فعل تینوں زمروں میں شریک کیے جا سکتے ہیں اور انہیں Participleسے موسوم کیا جا سکتا ہے۔
یونانیوں نے مطالعے کے حوالے سے صرف اپنی زبان کو ہی پیش نظر رکھا اور دیگر زبانوں پر توجہ نہ ہونے کے برابر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یونانی زبان کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو کم تر سمجھا۔ صرف انھوں نے یونانی زبان کی لغات بنانے پر زیادہ توجہ دی۔
قدیم ہند کی لسانی روایت مستشرقین کے توسط سے مغرب میں متعارف ہوئی اور مغرب کے ماہرین لسانیات نے ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ قدیم اور متوسط ہند آریائی ادوار میں سنسکرت قواعد دانوں اور لغت نویسوں کے لسانی کارنامے منظر عام پر نہ آسکے تھے اور مخطوطوں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ فن طباعت اور نشرواشاعت سے ناواقف تھے۔ اس لسانیاتی مواد سے وہ اپنے مقاصد یعنی ویدوں کی تفہیم تو پوری کرتے تھے لیکن برصغیر سے باہر کی دنیا اس سے استفادہ نہیں کرسکی تھی۔ پندرھویں صدی کے اواخر میں یورپی تاجروں نے برصغیر کا رُخ کیا اور ان کے ساتھ عیسائی مبلغ بھی یہاں پہنچے، رفتہ رفتہ ان کے سیاسی اور تجارتی مقاصد اس علاقے سے وابستہ ہوتے گئے جب انہیں سیاسی غلبہ حاصل ہوا تو انھوں نے یہاں کی زبانوں، تاریخ، مذہب اور کلچر میں دلچسپی لینا شروع کی۔ عیسائی مبلغین نے بھی یہاں کی زبانوں میں دلچسپی لی۔ اس طرح ان کی رسائی سنسکرت کے لسانیاتی خزانوں تک بھی ہوئی۔ ان میں سے بیشتر نے سنسکرت سیکھی، سنسکرت گرائمروں کا مطالعہ کیا۔ خود سنسکرت گرائمریں اور لغات مرتب کیں۔
یورپی مستشرقین نے سنسکرت کو اپنے علمی کارناموں کے توسط سے مغربی علما سے متعارف کرایا جس سے مغرب کے ماہرین لسانیات کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی اور لسانیات مطالعے کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا۔ سر ولیم جونز مستشرقین اور سنسکرت کے ماہرین میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ وہ ستمبر ۱۷۸۳ء میں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے کلکتہ پہنچا۔ اسے مشرقی علوم و ادبیات سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ نوجوانی میں ہی اٹھائیس زبانیں سیکھ چکا تھا جن میں عربی اور فارسی بھی شامل تھیں۔ ہندوستان پہنچ کر اس نے سنسکرت سیکھی اور اس پر عبور حاصل کیا۔ اس نے ہندوستان کی قدیم زبان، تاریخ اور کلچر پر منظم تحقیقات کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کی تحریک پر جنوری۱۹۸۴ء میں ایشیاٹک سوسائٹی (بنگال) کا قیام عمل میں آیا۔ اس سوسائٹی کے سالانہ جلسے میں اس نے اور دیگر مستشرقین نے ہندوستان کی زبانوں، تاریخ اور کلچر پر تحقیقی مقالات پیش کیے جس سے علم و ادب میں تحقیق کے نئے باب کھل گئے۔ اس سوسائٹی کی منصوبہ بندی کے تحت آثار قدیمہ، مخطوطات کی تلاش، چھان بین اور تحقیق و تدوین کی طرف توجہ دی گئی۔ اس کی شاخیں بمبئی اور مدارس میں بھی قائم ہوئیں جن کا الحاق بعد میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف گریٹ برٹن لندن سے ہوگیا۔ ایشیاٹک سوسائٹی کی تحقیقی سرگرمیوں کے دوررس اثرات مرتب ہوئے۔ یورپ کے علماء خصوصاً جرمن علما نے خود کو سنسکرت کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا اور ہندوستان، نیپال، سیلون، برما، سیام سے سنسکرت مخطوطات کو اکٹھا کیا اور ان قلمی نسخوں کا تقابلی مطالعہ کر کے ان کی تدوین کی۔ سر ولیم جونز نے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے اجلاس میں اپنے تیسرے سالانہ خطبے (فروری ۱۷۸۶ء) میں سنسکرت کی لسانی پختگی، اس کی عظمت و شکوہ اور یونانی، لاطینی اور فارسی سنسکرت کی گہری مماثلت اور ان زبانوں کے مشترکہ لسانی مآخذ کے موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ پڑھا جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ یہ خطبہ جدید لسانیات کے فروغ کا باعث بن گیا اور اس سے زبانوں کے تقابلی مطالعے کی راہیں ہموار ہوگئیں۔
برصغیر میں مستشرقین کی لسانی دلچسپی کے محرکات ابتداء میں مذہبی، تجارتی اور سیاسی نوعیت کے تھے۔ سولہویں صدی عیسوی میں عیسائی مبلغین یورپی مہم جوؤں کے ساتھ برصغیر میں پہنچنا شروع ہوئے۔ ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے یہاں کے مقامی باشندوں کی زبانیں سیکھنا اور ان کے رسوم و رواج، رہن سہن، کلچر اور تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عیسائی مشنریوں نے یہاں کی زبانوں میں دلچسپی لینا شروع کی اور مقامی زبانوں کی قواعد و لغات مرتب کیں۔ پروفیسر خلیل صدیقی یورپین کے مذہبی اور تجارتی اغراض و مقاصد کی نشان دہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: "پندرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں پرتگالی مہم جو، واسکوڈی گاما ہندوستان کے ساحل پر پہنچا اور پرتگالی مقبوضات بڑھنے لگے۔ اس کے بعد ڈچ،فرانسیسی اور برطانوی تجارتی کمپنیوں نے اس طرف کا رُخ کیا۔ تجارتی مفادات اور مسیحیت کے تبلیغی جذبات مشرق شناسی کے محرک ہوئے"7
یورپ کے تاجر یہاں پہنچے تو انھوں نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے مقامی باشندوں سے میل جول بڑھایا اور رفتہ رفتہ اپنی تجارت کو ہندوستان میں پھیلاتے گئے۔ انھوں نے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں بھی فراہم کر لیں اور اپنے تجارتی مفادات کے پیش نظر یہاں کی زبانوں میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈاکٹر ابواللیث کے خیال میں"ہندوستان کی سیاست اور زبانوں سے دلچسپی کے اور بھی محرکات تھے ان میں تجارت سب سے اہم تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی مفادات رفتہ رفتہ سیاسی رنگ اختیار کرتے گئے اور ان کو ہندوستان میں سیاسی غلبہ حاصل ہوتا گیاتو سیاسی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے ہندوستان کی مقامی زبانوں، تاریخ، رسوم و رواج اور کلچر میں دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ ڈنکن فارس کے قواعد ہندوستانی کے مقدمے کے آغاز کی عبارت سے ان اغراض و مقاصد اور ہندوستانی زبانوں میں دلچسپی کے محرکات کا اندازہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو اُردو زبان کی لسانی اور ادبی تحقیق کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ ۱۷۹۶ء میں ان کی اُردو قواعد (A Grammar of the Hindustani Language) کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ ان کی مجوزہ کتاب ہندوستانی لسانیات کی پہلی جلد کا تیسرا حصّہ تھی۔ اس کا پہلا حصّہ انگریزی ہندوستانی لغت تھی۔ دوسرا حصّہ بطور مقدمہ قواعد و لغت۱۷۹۸ء میں شائع ہوا۔ اٹھارویں صدی میں شائع ہونے والی دیگر قواعد میں فرگوسن کی ایک کتاب ہے جو دراصل ہندوستانی زبان کی لغت تھی اور اس میں ہندوستانی قواعد پر ایک مقالہ بھی شامل تھا۔ ہنری ہیرس کی ہندوستانی قواعد (Analysis, Grammar and Dictionary of Hindostani Language) ۱۷۹۱ء میں مدراس سے شائع ہوئی۔
انیسویں صدی میں شائع ہونے والی ہندوستانی (اُردو) زبان کی چند اہم قواعد کی فہرست مولوی عبدالحق (قواعد اُردو، مقدمہ) اور ڈاکٹر ابوللیث صدیقی (جامع القواعد، مقدمہ- ہندوستانی گرائمر مقدمہ) نے دی ہے۔ ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری (کتابیات قواعد اُردو) نے بھی اُردو زبان کی قواعد کی ایک طویل فہرست دی ہے جس میں سے چند اہم قواعد نویسوں کے نام ڈف، روبک، شیکسپئر، ہری ٹن، ارناٹ، ڈالسن، پلیٹس، فان کیو، کیگن وغیرہ ہیں۔
اُردو ہندوستانی قواعد کی تالیف کا مقصد ہندوستان آنے والے اور یہاں سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایسی زبان سکھائی جائے جو یہاں کی عام بول چال کی زبان تھی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈنکن فوربس نے اپنی تالیف قواعد ہندوستانی کے مقدمے کے آغاز میں کہا ہے کہ اُردو (ہندوستانی) کی یہ قواعد اُردو زبان میں نہیں ہیں بلکہ پرتگالی، ولندیزی، لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں ہیں۔ مقصد ہی ان زبانوں کے بولنے والوں کو اُردو (ہندوستانی) سکھانا تھا۔
اٹھارویں صدی میں قواعد کی تدوین کے ساتھ ساتھ ہندوستان پہنچنے والی یورپین نے لغات بھی مرتب کیں ان میں اُردو ہندوستانی زبان کی لغات بھی شامل ہیں۔ لغت نویسی کے اغراض و مقاصد بھی وہی تھے جو قواعد نویسی کے تھے یعنی عیسائیت کی اشاعت، تجارت کے فروغ اور سیاسی استحکام کے لیے مقامی زبانوں پر دسترس حاصل کرنا وغیرہ شامل تھے۔ ابتدائی طور پر لغات کے ساتھ چند صفحات قواعد کے بارے میں بھی شامل کر دیئے جاتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں مرتب کی گئی ان قدیم ترین لغات کا مختصر حوالہ پیش کیا گیا۔اب اٹھارویں اور انیسویں صدی کی دیگر چند اہم لغات کا حوالہ مختصر ذکر جن میں فرگوسن۔ جے کی"ڈکشنری آف دی ہندوستانی لینگوئج"، گل گرسٹ کی"اے ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی"، ٹیلر کیپٹن جوزف کی"ڈکشنری ہندوستانی اینڈ انگلش"، کار مائیکل"اُردو انگریزی لغت"، شیکسپئر "ڈکشنری ہندوستان اینڈ انگلش"، ڈاکٹر آدم "ہندی انگلش ڈکشنری"، تھامسن جے ٹی جوزف"اُردو انگریزی لغات"، ڈاکٹر فیلن ایس ڈبلیو"انگریزی اُردو قانونی و تجارتی لغات"، چارلس جیمز "نیو ہندوستانی انگلش ڈکشنری"، پلیٹس جان ٹی"اے ڈکشنری آف اُردو، کلاسیکل ہندی اینڈ انگلش"، وائٹ ورتھ، جارج کلیفورڈ"اینگلو انڈین ڈکشنری" وغیرہ شامل ہیں۔
یورپین لغت نویسوں کے مقاصد چاہے کچھ بھی رہے ہوں لیکن اس میں شک نہیں کہ لغت نویسی کی ذیل میں چند ایسی لغات بھی مدون ہوئی ہیں جو فن لغت نویسی کے حوالے سے معیاری لغات سے انگریزی داں طبقہ ہی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لغت نویسی کے اس سلسلے میں دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ نہ صرف ان کی تقلید میں اُردو میں لغات مرتب کی گئیں بلکہ ان لغت نویسوں میں سے چند کے معاونین نے اُردو لغت نویسی میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں جن میں فیلن کے معاون سید احمد دہلوی مولف "فرہنگ آصفیہ" نمایاں مقام رکھتے ہیں۔
اُردو میں لسانیات کے باقاعدہ آغاز کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو اٹھارویں صدی تک لسانیات سے اُردو داں طبقہ کی دلچسپی اتنی زیادہ نہ تھی۔ سترہویں صدی میں جب اہل مغرب برصغیر میں سنسکرت کے لسانیاتی خزانوں سے فیضیاب ہو رہے تھے اور اٹھارویں صدی میں مستشرقین ہندوستان کی زبانوں کے عمیق مطالعے کے نتیجے میں لسانیاتی کارہائے نمایاں سرانجام دے رہے تھے اور ہندو ماہرین لسانیات بھی اس لسانی مطالعے میں ان کے شریک کار تھے، تو اُردو داں طبقہ اس لسانیاتی سرگرمی سے یکسر بے خبر تھا۔
لسانیات سے اُردو داں طبقے کی عدم دلچسپی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ مقامی زبانوں، کلچر، تاریخ اور سنسکرت زبان و ادب سے ذہنی فاصلے رکھتے تھے اور ایرانی تہذیب و ثقافت اور فارسی زبان و ادب اور اس کے توسط سے عربی زبان و ادب سے تعلق قائم رکھے ہوئے تھے۔ فارسی عربی کے ماہرین کے علمی کارناموں سے ان کی واقفیت سطحی نوعیت کی تھی اس لیے کہ اگر وہ عربی زبان کے ماہرین کی شہرہ آفاق تصانیف کا بنظر غائر مطالعہ کرتے تو ان کے لسانیاتی کارناموں سے ضرور واقف ہوتے اور اس سے استفادہ کر کے اُردو لسانیات کی روایت کو آگے بڑھاتے تو اُردو لسانیات کی روایت ہندی اور مغربی لسانیات کی روایت کے مقابل آسکتی تھی۔
سراج الدین خان آرزو فارسی کے بہت اچھے عالم تھے۔ ان کی تصانیف فارسی زبان میں ہیں لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ برصغیر کے پہلے مسلمان عالم ہیں، جنہوں نے اپنی تصانیف میں جستہ جستہ ہی سہی، اُردو زبان کی خصوصیات،سنسکرت اور فارسی زبانوں میں مماثلتوں کی نشان دہی کی ہے۔ اُنھوں نے "نوادر الالفاظ"،"سراج اللغات"اور "مثمر"میں قواعد زبان اور سنسکرت اور فارسی میں لسانی مشابہتوں پر بحث کی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق:"آرزو کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ہندوستانی زبان کی لسانی تحقیق کی بنیاد رکھی، ہندوستانی فیالوجی کے ابتدائی قواعد وضع کیے اور زبانوں کی مماثلت کو دیکھ کر ان کے توافق اور وحدت کا راز معلوم کیا۔ یہ اصول ان کی کتاب مثمر میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغت کی کتابوں میں بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ قواعد زبان کی بحث میں خاص دلچسپی لیتے ہیں"8
سراج الدین خان آرزو نے اپنی لغات اور دیگر تصانیف میں سنسکرت اور فارسی لسانی مماثلتوں کی نشان دہی کی ہے۔ نوادرالالفاظ میں انھوں نے سنسکرت اور فارسی زبانوں کے مماثل الفاظ کی فہرست دی ہے اور مماثل ذخیرہ ئالفاظ کی بنیاد پر لسانی رشتوں کے اصول وضع کرتے ہوئے سنسکرت اور فارسی کو ہم نسب زبانیں قرار دیا ہے۔ محض مماثل ذخیرہ ئالفاظ کی بنیاد پر لسانی رشتوں کا تعین کرنا محلِ نظر ہے۔ زبانوں کے مماثل ذخیرہئ الفاظ کو لسانی اشتراک کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، یہ غیرلسانی نقطہ نظر ہے جس کے نتیجے میں آرزو نے دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والی زبانوں عربی (سامی) اور سنسکرت (آریائی) میں بھی لسانی رشتے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آرزو نے فارسی اور سنسکرت میں جس لسانی مشابہت کی نشاندہی کی ہے وہ حسن اتفاق سے مستشرقین کی لسانیاتی تحقیق کے مطابق درست ثابت ہوا لیکن آرزو نے محض لفظی مماثلت پر دھیان دیا تھا۔ فارسی اور سنسکرت کا لسانیاتی جائزہ نہیں لیا گیاتھا۔ جب کہ اس کے برعکس اٹھارویں صدی کے وسط میں کورڈو اور ولیم جونز نے سنسکرت اور دیگر آریائی زبانوں، جن میں قدیم فارسی زبان بھی شامل ہے، کے لسانی مطالعے کے بعد ان زبانوں میں لسانی رشتوں کی وضاحت کی تھی۔ آرزو فارسی کے بے مثل عالم تو تھے ہی لیکن سنسکرت سے ان کی علمی واقفیت اتنی نہ تھی جتنی مذکورہ مستشرقین کی تھی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ آرزو کو سنسکرت زبان میں کہاں تک دسترس تھی ا س کا صحیح اندازہ میں نہیں کرسکتا گمان غالب یہ ہے کہ ان کی واقفیت سرسری اور معمولی تھی۔ سرسید عبداللہ مزید لکھتے ہیں کہ آرزو کے مقالے میں ولیم جونز سنسکرت کا مستند علم رکھتے تھے۔ ان تمام اُمور کے باوجود یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ برصغیر کے مسلمانوں میں اُردو اور فارسی داں طبقے میں سنسکرت اور فارسی زبانوں میں لسانی اشتراک کی نشان دہی کرنے کے معاملے میں سراج الدین علی خان آرزو کو اولیت کا شرف حاصل ہے اور ان کی فارسی تصانیف میں زبانوں کے حوالے سے جو مباحث ملتے ہیں وہ ان کے لسانی شعور کا پتہ دیتے ہیں جیسے وہ اُردو میں دخیل الفاظ کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ الفاظ جو دوسری زبانوں سے اُردو میں رائج ہوجائیں انھیں اس صورت میں صحیح تسلیم کرنا چاہیے جیسے وہ عوام و خواص میں مروج ہیں اور ان کی اصل کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ دخیل الفاظ کے متعلق آرزو کے وضع کردہ قاعدے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ:"دخیل الفاظ کے تلفظ اور املا کے سلسلے میں آرزو کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں لفظ کی وہ صورت (مکتوبی یا ملفوظی) اختیار کی جائے جو اہل زبان (عوام و خواص دونوں) میں رواج پا چکی ہو۔ ایسے لفظوں کے لیے اصل زبان کی پیروی ضروری نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ نئی زبان میں اس کی وہ صورت سامنے رہنی چاہیے جو محض عوام ہی میں مروج نہ ہو بلکہ عام و خاص سب کے نزدیک مسلم ہو چکی ہو"9
محمد حسین آزاد( ۱۸۳۲ء - ۱۹۱۰ء) نے اپنے عہد کے مروجہ قیاسی تصورات کے برعکس اُردو کو مخلوط زبان قرار دینے کے بجائے اسے برج بھاشا کی بیٹی قراردیا۔ انھوں نے برج اور اُردو میں لسانی مماثلتوں کی نشان دہی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا۔ انہیں اس امر کا شعور ہے کہ ہرزبان کی اپنی مخصوص ساخت ہوتی ہے۔ البتہ وہ ہمسایہ زبانوں کے اثرات قبول کرتی رہتی ہیں۔ اُردو کے آغاز کے بارے میں محمد حسین آزادؔ کے نظریے کو بعد میں اُردو کے ماہرین لسانیات نے رد کر دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آزاد ؔنے طویل زبان کے تصور سے ہٹ کر پہلی بار اُردو کا مآخذ کسی دوسری زبان کو قرار دیا اور اُردو زبان کی ساخت میں اس کے مآخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں زبانوں میں لسانی روابط پیدا کرنے کا شعور تھا۔ محمد حسین آزادؔ کے اس لسانی شعور کا بھرپور اظہار "سخندان فارسی" میں بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے عمومی لسانیات کے مسائل سے تفصیلی بحث کی ہے۔ زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"وہ اظہار کا وسیلہ ہے کہ جو متواتر آوازوں کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے جنہیں تقریریا سلسلہ الفاظ یا بیان یا عبارت کہتے ہیں …… زبان (خواہ بیان) ہوائی سواریاں ہیں جن میں ہمارے خیالات سوار ہو کر دل سے نکلتے ہیں اور کانوں کے رستے اوروں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں …… تقریر ہمارے خیالات کی زبانی تعمیر ہے جو آواز کے قلم سے ہوا پر کھینچی ہے" 10
زبان کے بارے میں ہمارے ماہرین لسانیات نے اپنی اپنی آراء کے حوالے سے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان آفاقی نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق زمین سے ہے۔ زبان کبھی نہیں بدلتی صرف لہجہ بدلتا ہے، بولیاں بدلتی ہیں، محاورہ بدلتا ہے۔ زبان کو جو چیز سب سے مشکل بناتی ہے وہ محاورہ ہے۔
زبان انسانی عمل کی ابتدائی لیکن ایک مکمل صورت ہے۔ اس کی علامتیں عضائے نطق سے ادا ہونے والی آوازوں سے تشکیل پاتی ہیں اور مختلف زمروں اور سانچوں میں ترکیب پا کر پیچیدہ لیکن متوازن ساکھ کو جنم دیتی ہیں۔ علامتوں کے سیٹ کو زبان کے وجود سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ان سے معانی و مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ لیکن علامت اور معنی کا باہم ادراک اور رشتہ حقیقی اور منطقی نہیں ہوتا بلکہ اختیاری، مفاہمانہ اور متفکن الیہ ہوتا ہے۔ لسانی گروہ کی مرضی کے تابع ذہنوں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ یہ علامتیں بیک وقت عارضی محرکات کی قائم مقام بھی بن جاتی ہیں اور تاثرات اور جوابی عمل کی بدل بھی۔ اور مزید محرکات اور تاثرات کی داعی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بات چیت فوری طبعی محرک کی پابند نہیں رہتی۔ زبان کی ساکھ اتنی کامل اور اجزاء اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ بولنے والے کے لیے ہر قسم کے ذہنی، جذباتی تجربوں کو لسانی سانچوں میں ڈھالنے کے امکانات مہیا ہوجاتے ہیں۔ زبان خیالات کا ذریعہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ لفظوں اور فقروں کے توسط سے انسان کے ذہنی مفہوم و دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرے۔
مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ زبان ایک زندہ عمل ہے اور معاشرے کی ضروریات کے مطابق یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتاہے۔
٭٭٭
1 خلیل صدیقی ، زبان کیا ہے (دہلی : عاکف بک ڈپو ، 1984ء)،11۔
2 ڈاکٹر نصیر احمد خان، اُردو لسانیات(دہلی : اُردو محل پبلی کیشنز ، 1990ء)،15۔
3 پروفیسر خلیل صدیقی، زبان کا مطالعہ (مستونگ: قلات پبلی کیشنز 1964ء)، 24۔
4 ڈاکٹرمحی الدین قادری زور، ہندوستانی لسانیات(لاہور : مکتبہ معین الادب ، 1961ء)،21۔
5 ڈاکٹر نصیر احمد خان، اُردو لسانیات(دہلی : اُردو محل پبلی کیشنز ، 1990ء)،15۔
6 مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، المبین (لاہور: مکتبہ قادریہ1978ء)، 55۔
7 خلیل صدیقی ، زبان کیا ہے (دہلی : عاکف بک ڈپو ، 1984ء)،169۔
8 ڈاکٹر سید عبداللہ، مقدمہ مشمولہ نوادرالالفاظ تصنیف سراج الدین علی خان آرزو (کراچی: انجمن ترقی اُردو پاکستان، 1951ء)، 51۔
9 ایضاً، ۳۷۔
10 محمد حسین آزاد، سخندان فارسی (لاہور، مکتبہ ادب اُردو، سن،ن)، 16۔
|
0 |
http://journals.mehkaa.com/index.php/negotiations/issue/view/2 |
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |