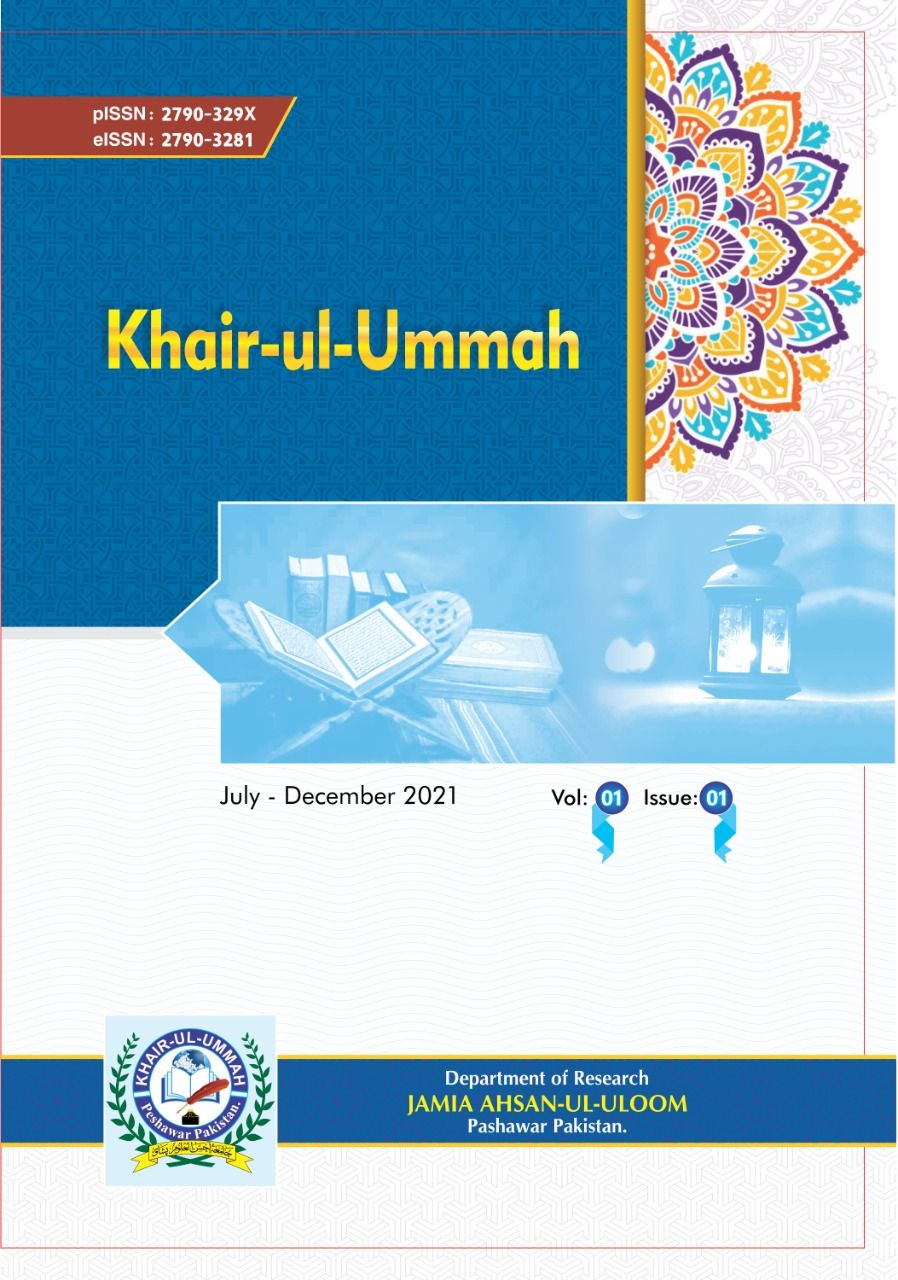1
1
2021
1682060062721_2072
69-80
https://khairulumma.com/index.php/about/article/download/8/7
وکالت کے لغوی معنی:
وکالت عربی زبان کا لفظ ہے ۔یہ بابِ"توکیل"سے اسمِ مصدر ہے۔اس کا مادہ"و ک ل" ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق دو(۲) معانی پر ہوتاہے:
(1) التفويض إلي الغير والإعتماد:(1)
یعنی کسی دوسرےشخص پر اعتماد کرکے اپنا کام سپرد کرنا۔
اسی معنی کے لئے قرآن مجید میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے؛ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾(2) أي "وفوّض إلى الله أمرك يا محمد، وثق به."(3)
ترجمہ: " اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے ۔یعنی اے محمد: اللہ تعالیٰ کو اپنا معاملہ سپرد کرو اور اُسی پر اعتماد کرو۔"
(2) الحفظ والقيام بالأمر:
یعنی حفاظت اور کسی کام کوسر انجام دینا، چنانچہ وکیل وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کرکے اپنا قائم مقام بنائے۔لسان العرب میں ہے:
"وكيل الرجل الذي يقوم بأمره لأن مؤكّله قد وكّل إليه القيام بأمره فهو موكولٌ بأمره."(4)
ترجمہ: "کسی آدمی کا وکیل وہ ہوتا ہے جو اُس کا سرانجام دیتا ہو، کیونکہ مؤکل نے اُن کو اپنے کام کی سرانجام دینے کے لئے وکیل بنایا ہے، چنانچہ اُس کو کان سپرد کیا ہوا ہاتا ہے۔"
قرآن مجید میں وکالت کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ◌﴾(5) أي ما أنت عليهم بحفيظ.(6)
ترجمہ: " ہم نے تم پر کتاب لوگوں (کی ہدایت) کے لئے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے (بھلے) کے لئے اور جو گمراہ ہوتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور (اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ "یعنی آپ اُن کے محافظ نہیں ہیں۔
غور کیا جائے تو دونوں معانی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہےکیونکہ کسی آدمی پر اعتماد کرکے کوئی کام سپرد کردینا "سبب" ہے اور پھر اس کی حفاظت اور انجام دہی "مسبّب"ہے۔"کشاف اصطلاحات الفنون" میں ہے:
الوكالة: بالكسر والفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد، وقد تطلق على الحفظ.(7)
ترجمہ: " وکالت (واو) کے زیر اور زبر کے ساتھ ،توکیل(باب تفعیل)کا اسم ہے، یہ سپرد کرنے اور اعتماد کے معنی کے لئے آتا ہے، اور کبھی کبھی حفاظت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔"
وکالت کے اصطلاحی معنی:
وکالت ایک جائز عقد ہے۔ فقہاء نے اس کی تعریف اور متعلقہ مسائل کااپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ذیل میں وکالت کی چند اصطلاحی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں:
احناف کے ہاں وکالت
بأنها:" إقامة الإنسان غيره مقامه في تصرف معلوم."(8)
ترجمہ:"کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے کسی معلوم تصرف (کام)میں اپنا قائم مقام بنائے۔"
لیکن اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ یہ جامع نہیں ہے ، چنانچہ امام زیلعی ؒ(م:743ھ) نے ان الفاظ کے ساتھ تعریف کی ہے:
"إقامة الإنسان مقام نفسه في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه. "(9)
ترجمہ: "کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی جائزاور معلوم تصرف (کام)میں اپنا قائم مقام بنائے، جس کا وہ خود مالک ہو۔"
اس تعریف کے ذریعے امام موصوف نے ماقبل تعریف پر ایک استدراک" في التصرف الجائز "کے ساتھ یہ کیا ہے،کہ صبی(لڑکا)جو ممیز(باشعور) ہو ،وہ اپنے مال کے ہبہ پر کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ اپنےمال کو خود ہبہ نہیں کرسکتالہذاکسی کو اس پر وکیل بھی نہیں بنا سکتا۔(10)
دوسرا استدراک "ممن يملكه " کے ساتھ یہ کیا ہےکہ فضولی(تیسرا شخص) کی توکیل بھی جائز نہیں کیونکہ وہ اس تصرف کا مالک نہیں(11)۔البتہ اگر مؤکل اجازت دے تو یہ تصرف نافذ ہو گا۔
مالکیہ کے ہاں وکالت:
مالکی فقہاء نے بھی قریب قریب اسی طرح تعریف کی ہے، چنانچہ امام قرافی مالکی ؒ(م: 684ھ) وکالت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:
"نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمْرَةٍ، وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ. "(12)
ترجمہ: "کوئی(کسی تصرف کا) حق دار کسی اور آدمی کو کسی ایسے کام کے لئے اپنا نائب بنائے جو بطورِ امر(order)نہ ہو اور نہ وہ کام عبادات میں سےہو اور مؤکل کی موت کے ساتھ بھی مشروط نہ ہو۔"
امام قرافی (م: 684ھ)کی تعریف میں دو قیود کا اضافہ ہے:ایک قید یہ ہے کہ وکالت صرف ان معاملات میں جائز ہے جن میں نیابت(قائم مقام بنانا) ہو سکتی ہو، چنانچہ نماز،روزہ اور وضوء میں وکالت جائز نہیں۔
دوسرا قید یہ ہے کہ مؤکل کی زندگی میں وہ تصرف ہو۔ اس کے ساتھ وصیت اور وکالت کے درمیان فرق بھی حاصل ہوجاتا ہے۔(13)
شوافع کے ہاں وکالت کی تعریف:
اکثر شافعی فقہاء نے وکالت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:
"تفويضُ شخص أمره إلي آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته. "(14)
ترجمہ:"کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو اپنا کوئی ایسا کام سپرد کرےجس میں نیابت جائز ہو، تاکہ وہ اس کام کو اس کی زندگی میں سرانجام دے۔"
حنابلہ کے ہاں وکالت:
حنابلہ وکالت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:
"اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ."(15)
ترجمہ: "کسی ایسے جائز تصرف جس میں نیابت ہو سکتی ہو، میں اپنے کسی مثل کےقائم مقام بنانے کووکالت کہتے ہیں۔"
قانون میں وکالت:
خلافتِ عثمانیہ میں رائج قانون مدنی (Civil law )میں وکالت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:
"الْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِيضُ أَحَدٍ فِي شُغْلٍ لِآخَرَ وَإِقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ
مُوَكِّلٌ وَلِمَنْ أَقَامَهُ وَكِيلٌ وَلِذَلِكَ الْأَمْرِ مُوَكَّلٌ بِهِ."(16)
ترجمہ:"کسی دوسرے شخص کو کوئی کام سپرد کرنا اور اس کو اس کا م میں اپنا قائم مقام بنانا وکالت ہے۔اس (سپرد کنندہ)شخص کو مؤکل ، قائم مقام شخص کو وکیل اور اس(سپرد کئے گئے )کام کو مؤکل بہ کہتے ہیں۔ "
وکالت کی اصطلاحی تعریفات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:
-
کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اپنا کام سپرد کرے۔
-
سپرد کنندہ کومؤکل کہتے ہیں اور جس کو کام سپرد کیا گیاہے اُسے وکیل کہتے ہیں۔
-
مؤکل جس کام کو سپرد کر رہا ہے وہ خود اس کام کا اہل ہو اور مالک ہو۔
-
کام میں نیابت جائز ہو یعنی عبادات کے قبیل سے نہ ہو۔
-
وہ کام شرعا جائز ہو۔
-
وہ کام معلوم ہو۔
-
مالکیہ کی تعریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سپردگی بطورِ امر(order) نہ ہو۔
کام وکیل کی موت کے ساتھ مشروط نہ ہو۔
قرآن کریم میں وکالت:
(۱) آیتِ زکو ٰۃ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ◌﴾(17)
ترجمہ:" صدقات (یعنی زکوٰۃ وخیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکُنان صدقات کا حق ہے۔ اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں (کے قرض ادا کرنے) میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کردیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ "
وجۂ استدلال:
اس آیت میں لفظ الْعَامِلِينَ(اس کام پر جانے والوں کا)وکالت کے جواز پر دلالت کرتاہے،کیونکہ عاملین کو حاکم اور بادشاہ، وکیل بنا کرزکوٰۃ جمع کرنے کے لئے بھیجتا ہے(18)۔ چنانچہ زکوٰۃ کی وصولیابی میں مستحقینِ زکوٰۃ کے لئے نائب مقرر کئے گئے ہیں اوروکالت کا یہی معنی ہے۔
احادیث میں وکالت:
عقد وکالت کا ثبوت جس طرح قرآن کریم سے ہوتا ہے اسی طرح احادیثِ رسول ﷺسے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی قولی وفعلی حدیثیں وکالت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اثار اور تعامل سے بھی وکالت ثابت ہوتی ہے۔ بطورِ نمونہ چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں:
(1) نبی کریم ﷺ زکوٰۃ جمع کرنے کے لئے اپنے نمائندوں کوبھیجا کرتے تھے، چنانچہ:
-
صحیحین میں سیدنا ابوہریرۃرضی اللہ عنہ (م:59ھ) سے روایت ہے:
*عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. (19)
ترجمہ: "نبی کریم ﷺنے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو صدقہ کے لئے بھیجا تھا۔"
-
اور سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ(م:60ھ) سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے:
*« استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. »(20)
ترجمہ: " رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ أسد کےایک آدمی کو بنی سُلیم کی زکوۃ ( اکٹھاکرنے)کے لئےعامل مقرر کیا تھا، جس کو ابن اللتبية کہا جاتاتھا، جب واپس آیا تو اُن کا محاسبہ کیا۔"
اجماع میں وکالت:
شریعتِ اسلامی کے سارے احکام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔کسی ایسے حکم کو جاری نہیں کیا جس کا کوئی فائدہ اور مصلحت نہ ہو، اور نہ کسی ایسے حکم کو ممنوع قرار دیا ہے جس میں لوگوں کے لئے مصلحت ہو۔خصوصاًمعاملات کے میدان میں لوگوں کی مصلحتوں کا بہت زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔عقد ِوکالت میں بھی لوگوں کی مصلحت اور فائدہ ہے کیونکہ ایک آدمی اپنے سارے اُمور ازخود سرانجام دینے سے قاصر ہوتاہے، اس وجہ سے عقدِ وکالت کو جائز قرار دیا گیاہے۔
اُمتِ اسلامیہ کے سارے فقہاء کا بھی عقدِ وکالت کے جائزہونے پر اجماع ہے، چنانچہ فقہ کی اکثر کتب میں یہ اجماع نقل کیا گیا ہے(21)۔
بیع مرابحہ کا تعارف:
مرابحہ کا لفظ "ربح" سے مأخوذہے۔ ربح کے لغوی معنی وہ زیادت ہے جو عقدِ بیع کی صورت میں حاصل ہو:
" الربح الزيادة الحاصلة في المبايعة." (22)
فقہاء کی اصطلاح میں بیع مرابحہ سے مراد یہ ہےکہ کسی چیز کو اس کی قیمتِ خرید سے زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کرنا: " هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. "(23)
ترجمہ: "کسی چیز کو اس کی اصل قیمت اور اضافی نفع کے ساتھ فروخت کرنا۔"
ابن جزی الکلبی المالکی(م:741ھ) نے اس کی صورت یہ بیان کی ہے:
" صاحبِ مال مشتری کو سامان کی قیمتِ خرید بتائےاور پھر اس سے ربح(منافع)اکھٹے طور پرلے ، یعنی یہ سامان میں نے دس دینار کے ساتھ خریدا ہے آپ مجھے ایک دینار یادو دینار نفع دیں۔ یا( نفع لینے میں) تفصیل بیان کرے، جیسے مجھے اس سامان کی قیمت کے ہر دینار پر ایک درہم نفع دیں، یا اس طرح کوئی اور تفصیل "(24)۔
بیع مرابحہ کارواج قدیم زمانے سے چلا آرہاہے ، اور فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ کاسانی(م: 587ھ) لکھتے ہیں:
" النَّاسُ تَوَارَثُوا هَذِهِ الْبِيَاعَاتِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَذَلِكَ إجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِهَا."(25)
ترجمہ: "لوگوں میں بیع کی یہ قسمیں(الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْوَضِيعَة) تمام ادوار میں بغیر کسی ناگواری کے چلی آرہی ہیں، یہ اِن کے جواز پر اجماع کی دلیل ہے۔"
بیع مرابحہ كے جواز كے شرائط:
-
-
ثمنِ اوّل مشتری ثانی کو معلوم ہو(26)۔
-
ربح (نفع) معلوم ہو(27)۔
-
رأس المال مثلی، مکیلی ، موزونی یا عددی ہو(28)۔
-
بیع مرابحہ میں سود(ربا) کا لزوم نہ ہو۔ مثلاً : مکیلی یا موزونی شئی کو اپنی جنس کے ساتھ فروخت کرنا ہو تواس میں ثمنِ اول پر زیادتی ناجائز ہے(کیونکہ یہ سود ہےجو حرام اور ناجائز ہے)اور ساتھ ہی نسیئة (اُدھار) بھی ناجائز ہے۔البتہ جب مخالف جنس کے ساتھ فروخت کرنا ہو تو مرابحہ جائز ہے(29)۔
-
بیع مرابحہ کے لئے عقدِ اوّل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ثمنِ اول پر زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے کا نام ہے۔ جب عقدِ اول صحیح نہ ہو (یعنی فاسد ہو)تو اس میں ملکیت مبیع کی قیمت(مارکیٹ ریٹ) کے ساتھ ثابت ہوتی ہے(30)۔
بیع مرابحہ میں رأس المال اور اخراجات كا حكم:
رأس المال سے مراد سامان کی وہ قیمت ہے جس پر مشتری اوّل (بیع مرابحہ میں بائع)نے چیز خریدی ہے۔اب بیع مرابحہ میں رأس المال کے ساتھ وہ سارے بلا واسطہ اخراجات(Direct Expenses) بھی شامل ہیں جو اس سامان کے حصول تک لازم اور واجب ہوتے ہیں ۔البتہ بالواسطہ اخراجات (Indirect Expenses) ان میں شامل نہیں ہوتے۔
براہِ راست اخراجات میں سامان کی پہلی مرتبہ خریداری سے لے کر گاہک کے قبضے میں آنے اور دوبارہ خریداری تک کے اخراجات شامل ہیں۔جس میں نقل وحمل(Transportation)، حفاظت (Warehouse)، محاصل (Duties)اور انشورنس کے اخراجات شامل کئے جاسکتے ہیں۔لیکن وہ اخراجات جو اس سامان پر براہِ راست نہیں آتے ، جیسے ملازمین کی تنخواہیں ، بجلی کے بل، عمارت کا کرایہ وغیرہ ، انہیں سامان کی لاگت میں شامل نہیں کئے جاسکتے (31)۔ چونکہ مرابحہ میں خریدے گئے سامان کی قیمت مع لاگت بتلانا ضروری ہے،لیکن اس صورت میں بائع یہ نہیں کہے گا کہ اس کی قیمت یہ ہےبلکہ وہ کہے گا کہ مجھے یہ سامان اتنے پیسے(اصل قیمت +اخراجات) پر پڑا ہے اور میں آپ کو اتنے ربح کے ساتھ فروخت کر تا ہوں (32)۔لہذا اگر سامان کی لاگت معلوم نہ ہو تو اسے بطورِ مرابحہ آگے فروخت کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ اس کو "بیع مساومہ " کے ساتھ فروخت کرنا صحیح ہوگا۔
اسلامی بینکوں میں مرابحہ طریقۂ تمویل:
بیع مرابحہ بنیادی طور باضابطہ تمویلی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ "عقدِ امانت "ہے؛ کیونکہ اس میں بائع گویا یہ کہہ رہا ہوتاہے کہ میں مشتری سے اتنی مقدار کا منافع کما رہا ہوں۔البتہ بعض ضرورتوں کی وجہ سے مرابحہ بھی تمویلی طریقہ کے طور پر اختیار کیا جاسکتاہے۔ چنانچہ اسلامی بینکاری میں مرابحہ کی پریکٹس بطورِ تمویل جاری ہو گیا ہے، جسے "المرابحة للآمر بالشراء"کہتے ہیں۔
المرابحة للآمر بالشراء کی تعریف:
"هي طلب الفرد أو المشتری من شخص آخر (أو المصرف) أن یشتری سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك علي أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن علي دفعات أو أقساط تبعا لإمكانياته وقدرته المالية."(33)
ترجمہ: "مرابحہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یا خریدار دوسرے آدمی (یا بینک) سے معیّن اور مخصوص صفات کے ساتھ موصوف سامان کا مطالبہ کرتاہے، اس بنیاد پر کہ وہ (خریدار)وعدہ کرتا ہےکہ وہ یہ سامان بیع مرابحہ کے ساتھ اس (دوسرے آدمی یا بینک)سے خریدے گا، اور یہ (اصل قیمت کی )نسبت(کی زیادتی کے ساتھ) یا (دونوں کے مابین) طے شدہ منافع ہو گا، اورسامان کی قیمت قسطوں کے ساتھ اپنی مالی قدرت اورحیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ "
مرابحہ کا یہ عقد مندرجہ ذیل مراحل سے گزر کر تکمیل کو پہنچتاہے:
-
گاہک یا خریدار اسلامی بینک یامالیاتی ادارے کو اپنی رغبت ظاہر کرتاہےکہ میں فلاں سامان مرابحہ کے ذریعے آپ کے واسطےسے خریدنا چاہتاہوں۔ بینک یا ادارہ گاہک سے وعدہ لیتاہے کہ اگر ہم نے مارکیٹ سے مطلوبہ سامان خرید لیا تو پھر بعد میں یہ آپ نے خریدنا ہوگا۔اس وعدے کا مقصد یہ ہوتاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بینک یا ادارہ وہ سامان خرید لے اور پھر گاہک اُسے خریدنے سے انکار کردے۔
-
بینک یا ادارہ مطلوبہ سامان مارکیٹ سے خریدتا ہے۔ عموماً ادارہ اسی گاہک کو خریداری کے لئے اپنا وکیل بناتاہے، چنانچہ گاہک بطورِ وکیل سامان کی خریداری کرتاہے۔ اس کے لئے عام طور پر فریقین کے درمیان وکالت (Agency)کا تحریری معاہدہ کیا جاتاہے۔
-
گاہک مطلوبہ سامان خرید کر اس پر قبضہ کرتاہے۔ وکیل کا یہ قبضہ بینک یا ادارے کا قبضہ ہوتاہے۔ چنانچہ اگر یہ سامان گاہک کی خریداری سے پہلے ہلاک ہو جائے تو یہ بینک یا ادارے کا نقصان ہوگا۔
-
گاہک مطلوبہ سامان خریدنےکے بعد بینک کو اطلاع دیتاہے کہ آپ کے وکیل کی حیثیت سے فلاں سامان خرید کر اس پر قبضہ کر چکاہوں۔اس کے بعدگاہک بینک کو آفر (Offer) کرتاہے کہ وہ اُسے یہ سامان مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کردے ۔ فقہی اصطلاح میں اسے "ایجاب" کہتے ہیں۔
-
بینک یاادارہ اس ایجاب کو "قبول" کرتاہےجس سے بینک اور گاہک کے مابین مرابحہ کا عقد تکمیل کو پہنچ جاتاہے۔ اب اس سامان کی ملکیت اور رِسک دونوں گاہک کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔
وکالت کا شرعی وقانونی جائزہ:
اسلامی بینک اور اس کے گاہک کے مابین " المرابحة للآمر بالشراء " کے معاملے میں عقدِ وکالت کی دو صورتیں ہیں:
پہلی صورت یہ ہے اسلامی بینک مطلوبہ سامان کی خریداری کے لئے اپنے اس گاہک کے علاوہ کسی دوسرے فرد یا ادارے کو اپنا وکیل بنائے۔ جب وکیل واقعی خریداری کرے اور سامان بینک کی ملکیت اور ضمان میں آجائے تو پھر اپنے گاہک کے ساتھ " مرابحة "کا معاملہ کرے ۔ اس صورت میں کو ئی قباحت نہیں جبکہ سامان بینک کی ملکیت اور قبضے میں آچکا ہو۔کیونکہ غیر مملوکہ سامان کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:
" عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك ".(34)
ترجمہ: "سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نےرسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا : کہ ایک شخص مجھ سے کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہوتی تو کیا میں ایسی چیز کو فروخت کرسکتاہوں؟رسول اللہﷺ نے فرمایا ایسی چیز نہ بیچو جو تیرے پاس موجود نہ ہو۔"
اسی طرح غیر مقبوض سامان فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے:
" عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ لِي: «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»"(35)
ترجمه: " سیدنا حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ میں نےرسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا :میں سامان بیچتاہوں تو میرے لئے کیا حلال ہے اور کیا اور کیا حرام ہے ، رسول اللہﷺ نے فرمایا: جب تو کو ئی چیز فروخت کرنا چاہے تواُس پر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ "
دوسری صورت یہ ہے کہ بینک یا ادارہ اپنے گاہک کو ہی اس سامان کی خریداری کے لئے اپنا وکیل بنائےجس کو بعد میں اس گاہک کو فروخت کرے گا۔
اس صورت میں بینک یا ادارہ سامان کو خود خرید لے یا اس گاہک کے علاوہ کسی اور فرد یا ادارے کو اس کا وکیل بنائے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہواور بینک یا ادارہ مجبور ہو کہ اس گاہک کو ہی خریداری کے لئے وکیل بنائےتو جائز ہے۔ وكيل اس صورت ميں اپنے لئے بیع کا مالک نہیں ہوگا،یعنی اپنے آپ کو وہ سامان فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ : "الواحدُ لا يتولّي طرفي العقد." (36) بلکہ بینک یا ادارہ بعد میں اس کو فروخت کرے گا۔چنانچہ معاییرِ شرعیہ کے دفعہ 3/1/3 میں مذکور ہے:
"الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسهامباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريقِ وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجاء لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة. ولا يتولّي الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين."(37)
ترجمہ: "اصل یہ ہے کہ ادارہ بائع سے سامان بذاتِ خود خریدے گا، ادارے کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اس کام کے لئے آمر بالشراء(گاہک) کے علاوہ کسی دوسرے کو وکیل بنائے، گاہک (الآمر بالشراء) کو شدید ضرورت کے بغیر اس کام کے لئے وکیل نہیں بناسکتا، اب (اگر گاہک کو وکیل بنایا گیا تو)وکیل اپنے لئے یہ سودا نہیں کرے گا، بلکہ جب بینک یا ادارہ سامان کو اپنی ملک میں لے لے،تو اس کے بعد ادارہ کو فروخت کرے گا۔"
جب گاہک وکیل کی حیثیت سے بینک کے لئے سامان خریدے تو جب تک بینک کا قبضہ ثابت نہ ہو(بینک کے لئے قبضہ وکیل بالقبض کی حیثیت سے یہی وکیل بھی کر سکتاہے) یہ وکیل کے ہاں امانت ہے، لہذا اگر سامان وکیل کے ہاں ازخود ہلاک (ضائع )ہو جائےاور اس کا اپنا فعل اس میں شامل نہ ہوتو اس کا کوئی ضمان وکیل پر نہیں ہوگا(38)۔
جب وكيل بينك سے یہی سامان خریدنا چاہے تو وہ بینک سے "ایجاب (Offer)"یعنی سامان کی خریداری کا مطالبہ کرے گا اگر بینک قبول (Accept)کرے تو گاہک اور بینک کے درمیان یہ ایک نیا عقد ہو گایہ عقدِ مرابحہ ہے، جس کا سابق عقد سے کو ئی تعلق نہیں یعنی وکالت کا عقد مرابحہ کے عقد سے مستقل ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں عقدوں کے مابین ارتباط (Correlation) نہ ہونے پائے؛ کیونکہ سابق عقد میں گاہک وکیل کی حیثیت سے سامان خرید رہا تھااور وکیل امین ہوتا ہے لہذا ضمان بینک کے ذمہ ہوگا ۔اب گاہک بینک سے اصیل کی حیثیت سے خرید رہا ہے، لہذا خریداری کے بعد ضمان بھی گاہک کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
مرابحہ کی صحت کے لئے یہ بنیادی شرط ہے کیونکہ اگرگاہک کو خریداری کے لئے وکیل بنانےسے لے کر عقدِ مرابحہ کے منعقد ہونے سے پہلے تک ضمان بینک کا نہ ہو تو "ربح ما لم يضمن"(39)لازم آتاہے جو کہ ناجائز ہے۔چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن ». (40)
ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے قرض اور بیع، ایک سودا میں دو شرائط اور ایسی چیز کامنافع جس کا ضمان نہ سے منع فرمایا ہے۔"
اسی طرح یہ تمویلِ ربوی (Interest Based Finance)ہے۔لہذاگاہک کو وکیل بنانے اور عقدِ مرابحہ کےمرحلے کے مابین واضح فرق ہونا ضروری ہے تاکہ دوضمانوں میں تداخل لازم نہ آئے۔اسی نکتہ کی وضاحت معاییر شرعیہ میں کی گئی ہے:
" يجب الفصلُ بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل المدّة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقدِ المرابحة للآمر بالشراء من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع. "(41)
ترجمہ: "دونوں ضمانوں کے مابین فصل ضروری ہے یعنی مؤسسۃ کے ضمان اورگاہک کے ضمان کے مابین، جو مؤسسۃ کی جانب سے مؤسسۃ کے لئے سامان کے خریدنے کا وکیل ہے، اور ایک ایسی مدّت درمیان میں حائل ہونی چاہئے جس کے ذریعے وکالت کے نافذ کرنے اور عقدِ مرابحہ کے مابین فصل ہو سکےیعنی ایک نوٹس وکیل (گاہک) کی طرف سے جائے گاکہ میں نے وکالت نافذ کردی ہےاور سامان خرید لیاہے(اب میں حسبِ وعدہ آپ سے یہ سامان خریدنا چاہتاہوں)، پھر ایک نوٹس مؤسسۃ کی طرف سے فروخت کرنے کا جاری ہو گا۔"
خلاصۂ بحث
بیع مرابحہ در حقیقت ایک غیر تمویلی(Non-Financial)عقد ہے ؛ کیونکہ یہ دراصل امانت کا عقد (Credit Contract) ہوتاہے۔لیکن موجودہ زمانے میں اسلامی بینکوں اور دوسرے اسلامی مالیاتی اداروں نے ضرورت کی بناء پر بیع مرابحہ شروع کیا ہے جس کو "مرابحة للآمر بالشراء "کہتے ہیں۔اس میں بینک آمر(گاہک) کے لئےمطلوبہ سامان مہیا کرتا ہے، خواہ بینک از خود خرایداری کرے یا کسی کو وکیل بنائے۔ جب سامان بینک کے قبضہ میں آجائے اس کے بعد آمر بالشراء کے ساتھ مرابحہ کا عقد کرتا ہے۔ اگر بینک انتہائی مجبوری کی حالت میں آمر ہی کو سامان کی خریداری کے لئے وکیل بنائے تو پہلے بحیثیتِ وکیل آمر بینک کے لئے سامان کی خریداری کرے گا۔ جب وکیل بینک کے لئے خریداری کرے تو سامان بینک کے ضمان میں داخل ہو جاتاہے لہذا اگر وکیل کی تعدّی کےبغیر ہلاک ہو جائے تو یہ نقصان بینک کا شمار ہوگا۔ وکیل خریداری کرنے کے بعد بینک کو خریداری اور قبضہ کا نوٹس کرے گا اور ساتھ ہی مرابحہ کے ذریعے خریدنے کاایجاب (Offer) بھی کرے گا۔ بینک بھی ایک علیحدہ نوٹس کے ذریعے اس کو قبول(Accept) کرےگا، جب بینک قبول کرے، تو دونوں پارٹیوں کے مابین عقدِ مرابحہ اپنے تکمیل کو پہنچ گیا۔ مرابحہ کی تکمیل کے بعدسامان کا ضمان بینک سے منتقل ہو کر آمر بالشراء کے ذمے آجاتاہے۔
حواشی و حوالہ جات
پی ایچ ڈی، علومِ شریعہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔
لیکچرر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹذیز، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔
پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علومِ اسلامیہ، گومل یونیورسٹی، ڈیرہ اسماعیل خان۔
1() الفراهيدي ، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبد الرحمن، البصري (م: 170ھ)كتاب العین، 403:5، دار ومكتبة الهلال، بدون تاريخ طبع. / الفارابي، إسماعيل بن حماد، أبو نصر،الجوهري (م: 393هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب اللام فصل الواو، مادة: وكل، دار العلم للملايين، بيروت 1407 هـ - 1987ء. / ابن منظور الأفريقي، أبو الفضل، محمد بن مكرم، جمال الدين (م: 711هـ)، لسان العرب، باب اللام، فصل الواو، مادة: "وکل" حوالہ سابق ۔/ المناوي ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الحدادي، القاهري (م: 1031هـ)، التوقيف على مهمات التعاريف ، باب الواو فصل الکاف فصل اللام مادة: "وکل"، عالم الكتب، القاهرة، 1410هـ-1990ء.
2() الاحزاب33: 3
3()الطبري، أبی جعفر،محمدبن جریر(م:310ھ)، جامع البيان عن تاويل آي القران ، تحقق: أحمد محمد شاكر ، 20: 204، مؤسسة الرسالة، بيروت1420 ه.
4() ابن منظور الأفريقي، أبو الفضل، محمد بن مكرم، جمال الدين (م: 711هـ)، لسان العرب، باب اللام، فصل الواو، مادة: "وکل" حوالہ سابق ۔
5() الزمر41: 39
6()الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (م: 311هـ)، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 356: 4، عالم الكتب، بيروت 1408 هـ - 1988م.
7() التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر، الفاروقي، الحنفي (م: بعد1157هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي،: 2، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1996ء
8() ابن امير الحاج، أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن محمد(م:879ھ)، التقرير والتحبير، 29: 2، دارالكتب العلمية، بيروت 1403ھ ./ أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود، البخاري، الحنفي (م: 972ھ)، تيسير التحرير، 44: 2، دار الفكر، بيروت بدونِ ترايخ طبع. / البابرتي، أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود، أبو عبد الله، الرومي (م: 786هـ)، العناية شرح الهداية، 499: 7، دارالفكر، بيروت بدونِ ترايخ طبع./ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (م: 1078هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 221: 2،دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبع وتاریخ۔
9() الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين، الحنفي (م: 743 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 254: 4، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، 1313ه.
10() علي حيدر(م: 1353هـ)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 493: 3، دار الجيل، بيروت،1411هـ - 1991م.
11() علي حيدر(م: 1353هـ)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 403:1.
12() القرافي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، المالكي (م: 684ھ)، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، 55: 4، عالم الكتب، بيروت بدون تاريخ طبع.
13() الحطاب، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، شمس الدين، المالكي (م: 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،181: 5، دار الفكر، بيروت 1412ه .
14() السنيكي، ابو يحي، زكريابن محمد زكريا، الأنصاري(م: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 260:2، دارالكتب العلمية، بيروت، 2000م./ البكري الدمياطي، أبو بكر ،عثمان بن محمد شطا، الشافعي (م:1310ھ)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، 100: 3، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، بيروت ، 1418ه. / أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، 422: 2، دارالفكر، بيروت 1415ه-1995م .
15() البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، الحنبلى(م: 1051هـ)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، 184: 2، عالم الكتب، بيروت، 1414ه-1993م۔/ البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس، الحنبلى(م: 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، 461: 3، دارالكتب العلمية، بيروت بدون تاريخ طبع.
16() مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية ،280: 1، مادة:1449.
17() التوبة 9:60
18() القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر، شمس الدين (م: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، 177: 8، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1384هـ - 1964 م.
19() یہ روایت امام بخاری (م: 256هـ) نے أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه کی سند سے كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله (التوبة: 9: 60)، 122: 2، رقم الحدیث: 1468،کے تحت ذکر کی ہے۔(البخاري، أبو عبدالله، محمد بن إسماعيل بن ابراهيم(م: 256هـ)، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، بيروت، 1422ه.)۔اور امام مسلم (م: 261هـ)نےبطریق زهير بن حرب، حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة کی سند سے كتاب الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، 676: 2، رقم الحدیث:983،کے تحت ذکر کی ہےاور الفاظ امام مسلم کے ہیں۔( القشيري، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج، النيسابوري ، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.)
20() یہ روایت امام بخاری نے يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهکی سند سے كتاب الأمارة، باب: تحريم هدايا العمال، 2: 130، رقم الحدیث: 1500کے تحت ذکر کی ہے(صحیح بخاری،حوالہ سابق)۔ اور امام مسلم نے أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر ( واللفظ لأبي بكر ) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعديکی سند سے ا468: 3، رقم الحدیث: 1832 کے تحت ذکر کی ہے(صحیح مسلم، حوالہ سابق)۔
21() ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المصري (م: 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،141: 7، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ۔ / السنيكي، أبو يحيى، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين (م: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 260: 2، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ/ الحطاب، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، شمس الدين، المالكي (م: 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 181: 5، دار الفكر، بيروت 1412ه ./ الشرواني، عبد الحميد، العبادي، أحمد بن قاسم(م: 992ه)، حواشي الشرواني والعبادي علي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 294: 5، المكتبة التجارية الكبرى مصر، بدون تاريخ طبع.
22()الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (م: 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، ص: 158، دار المعرفة، بيروت، س ن.
23()الزحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الإسلامي وأدلته،5: 3765.
24()ابن جزي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله(م: 741هـ)، القوانين الاحكام الشرعية و مسائل الفروع الفقهية، ص279، دارالعلم للملايين، بيروت.
25()الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي (م: 587ھ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 5: 220.
26() ايضًا۔
27()الزحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الإسلامي وأدلته،5: 3768.
28() ايضًا۔
29() السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة (م: 483هـ)، المبسوط، 13: 85.
30()الزحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الإسلامي وأدلته،5: 3770.
31() صمدانی، اعجاز احمد، ڈاکٹر، اسلامی بینکوں میں رائج مرابحہ کا طریقِ کار، ص31، 32 ، ادارہ اسلامیات، کراچی 1427ھ= 2006ء۔
32()الزحيلي، وهبة بن مصطفي، الفقه الإسلامي وأدلته،5: 3771.
33() أميرة عبداللطيف مشهور، الدكتورة، الإستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ص334، مكتبة بدبولي، القاهرة 1991م.
34() یہ حدیث امام ابن ماجہ (م: 273هـ) نے محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم بن حزام کی سند سے باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم الحديث: 2187 کے تحت ذکر کی ہے۔اور شیخ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح قرار دی ہے۔(القزويني، ابن ماجه أبو عبدالله، محمد بن يزيد (م: 273هـ) ، سنن ابن ماجه، ، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، س ن.)
35() یہ حدیث امام نسائی اپنی سنن کبریٰ میں کی إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، وعن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزامسند سے كتاب البيوع ، باب بيع ما ليس عندك، 180: 5، رقم الحديث: 6163.کے تحت ذکر کرتے ہیں۔( السنن الكبرى للنسائي، حوالہ سابق)
36()ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد (م: 861هـ)، فتح القدير، 8: 71.
37()المعايير الشرعية، المعيار الشرعي، المرابحة للآمر بالشراء، رقم (8) بند3/1/3.
38()الكاساني ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي (م: 587ھ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 34:6./ غياث الدين البغدادي، أبو محمد، غانم بن محمد الحنفي (م: 1030هـ)، مجمع الضمانات، ص251./ علي حيدر(م: 1353هـ)،درر الحكام شرح مجلة الأحكام،287:2./ ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (م: 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 87: 4./ الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، الشافعي (م: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 254:3 ./ ابن قدامة، أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الحنبلي (م: 620هـ)، المغني لإبن قدامة، 75:5.
39() ربح ما لم یضمن کا مطلب یہ کہ ایسا مال فروخت کرناجس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو، چنانچہ یہ بائع اول کے ضمان میں ہوتاہے لہذاا یسا مال پہلے اپنے قبضے میں لانا ہو گا پھر آگے فروخت کرنا جائز ہے۔
40() یہ حدیث امام نسائی نے إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهکی سند سے كتاب البيوع، باب: سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، 6: 66، رقم الحديث: 6180کے تحت روایت کی ہے۔( السنن الكبرى للنسائي، حوالہ سابق)
41()المعايير الشرعية، المعيار الشرعي، المرابحة للآمر بالشراء، رقم (8) بند5/1/3.
75
-
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |