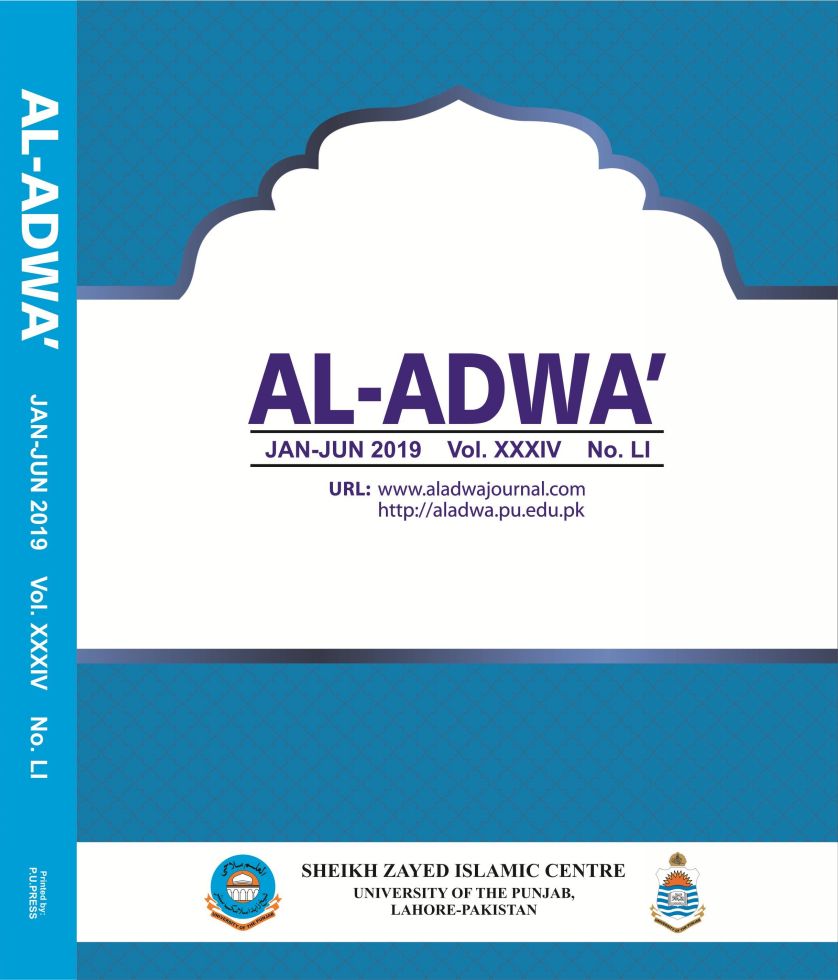37
58
2022
1682060078052_3014
1-18
https://journal.aladwajournal.com/index.php/aladwa/article/download/582/418
https://journal.aladwajournal.com/index.php/aladwa/article/view/582
کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنے کے لیے تاریخ و ادبیات اور لسانیات میں یہ بات موجود رہی ہے کہ ایک ہی چیز کی وضاحت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور ایک ہی لفظ کے ذریعے مختلف موقعوں پر مختلف رویوں کا اظہار ہوتا رہا ہے۔
قرآن کریم میں بھی ایسے کئی مواقع پر الفاظ کے مختلف اور متقارب معنی کی رنگا رنگی پائی جاتی ہے جو کہ قران مجید کے بدیع اسلوب اور اعجازی پہلو کی آئینہ دار ہے۔چونکہ عربی خالصتاً عربوں کی زبان ہے تو اسے سمجھنے کے لیے عربی لغات، عربی شاعری اور عربی محاورات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔عرب معمولی سے معمولی فرق کا اظہار الگ لفظ سے کرتے تھے۔عربی زبان میں مترادفات دیگر زبانوں کی بانسبت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں،مثلاً:
يُقَالُ بَرَأَ اللَّه الْخَلْق، وَفَطَرَهُمْ، وجَبَلهَم، وَخَلَقَهُمْ، وَأَسَرَهُمْ وَذَرَأَهُمْ، وَأَنْشَأَهُمْ، وكَوَّنهم، وَصَوَّرَهُمْ، وَسَوَّاهُمْ، وأوَجْدَهم، وَأَحْدَثَهُمْ، وَأَبْدَعَهُمْ، وَأَبْدَأَهُمْ.1
عربی زبان کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے بہت سے معانی استعمال ہوتے ہیں،جو کہ مشترک الفاظ کہلاتے ہیں۔مثلاً:السوء کا لفظ گیارہ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔2
ذیل میں ایسے الفاظ کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں جو مشترک الفاظ ہیں اور اپنے اندر متعدد معنی و مفہوم رکھتے ہیں نیز ان کےتفسیری اختلافات اور توجیہات کو بیان کیا جاتا ہے۔یہ الفاظ قرآنی سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے لیے گئے ہیں :
الدین:
﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّين﴾ 3
"مالک روز جزا کا۔"
اس آیت میں "الدین " کا لفظ مشترک ہے۔4 اس کا مطلب ہے اعمال پر جزا اور اعمال پر حساب۔حضرات ابن مسعود،ابن عباس، ابن جریج اور ابن قتادہ وغیرہم نے اسی طرح فرمایا ہے۔نبی کریمﷺ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد بھی ہے: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقّ﴾5 اس آیت میں دین سے مراد حساب ہے۔فرمایا: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾6 اور فرمایا﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾7 اور فرمایا:﴿إِنَّا لَمَدِينُونَ﴾8 یعنی ہم جزا دیے جائیں گے اور ہمارا محاسبہ کیا جائے گا۔لبید نے کہا:
حَصَادُكَ يَوْمًا مَا زَرَعْتَ وَإِنَّمَا ... يُدَانُ الْفَتَى يوما كما هو دائن9
"تو اس دن وہی کاٹے گا جو تو نے بویا، ان کو جزاء دی جائے گی جو وہ کرنے والا ہو گا۔"
ایک اور نے کہا:
وَاعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ مُلْكَكَ زَائِلٌ ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ10
"جان لو کہ تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے اور جان لو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔"
اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ :
دِنْتَهُ بِفِعْلِهِ دَيْنًا (بِفَتْحِ الدَّالِّ) وَدِينًا (بِكَسْرِهَا) جَزَيْتَهُ11
"یعنی میں نےاسے جزا دی۔"
اسی سے ہے "الدیان" اللہ تعا٫لی کی صفت ہے یعنی جزا دینے والا۔
الدین سے مراد فیصلہ ہے۔یہ بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔اسی معنی میں طرفہ کا قول ہے:
لَعَمْركَ مَا كَانَتْ حَمُولَةَ مَعْبَدٍ ... عَلَى جُدِّهَاحَرْبًا لِدِينِكَ مِنْ مُضَرْ12
"تیری عمر کی قسم معبد کے اونٹ کنویں پر تیرے فیصلے کی وجہ سے مضر قبیلہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں تھے۔"
دین کے یہ تینوں معانی قریب قریب ہیں۔ زهير بن أبي سُلمى کا قول ہے:
لَئِن حَلَلْتَ بِجَوٍّ في بنی أَسَدٍ ... في دِينِ عَمْرٍو وَمَالتْ بَيْنَنَا فَدَكُ13
دین کا معنی اطاعت بھی ہے۔اس معنی میں عمر بن کلثوم کا یہ شعر بھی ہے:
وَأَيَّامٍ لَنَا غُرٍّ طِوَالٍ ... عَصَيْنَا الْ٫٫٫مَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا14
"ہمارے لیے روشن لمبے دن تھے۔ہم نے ان میں بادشاہ کی اطاعت کرنے میں نافرمانی کی۔"
ثعلب نے کہا کہ" دان الرجل" کا مطلب ہے کہ اس نے اطاعت کی اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس نے نافرمانی کی۔دان کا لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی عزت پائے اور اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی ذلیل ہواور اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی غالب آئے۔پس یہ لفظ اضداد میں سے ہے15 الدین کا اطلاق عادت اور شان پر بھی ہوتا ہےجیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:
كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا16
جیسا کہ تیری شان ام الحویرث کی طرح ہے۔ مثقب نے اپنی اونٹنی کی عادت کے بارے میں کہا:
تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي... أَهَذَا دِينُهُ أَبَدًا وديني17
الدین بادشاہ کی عملداری کو بھی کہتے ہیں۔زہیر نے کہا:
لَئِنْ حَلَلْتَ بِجَوٍّ فِي بَنِي أَسَدٍ ... فِي دِينِ عَمْرٍو وَحَالَتْ بَيْنَنَا فَدَكُ 18
اگر تو بنی اسد میں جو کے مقام پر عمرو کی عملداری کے لیے اترے گا اور ہمارے درمیان فدک کا مقام حائل ہو۔الدین سے مراد بیماری بھی ہے۔لحیانی سے مروی ہے،اس نے کہا:
يَا دين قلبك من سلمى وقد دينا19
اس میں دین بمعنی مرض استعمال کیا ہے۔
الصلاۃ:
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ 20
"جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔"
صلاۃ کا لفظ مشترک ہے۔تفسیر قرطبی میں امام صاحب فرماتے ہیں: "فَهِيَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ"21
صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے اور صلی یصلی سے مشتق ہےجس کا معنی ہے "دعا کرنا":
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ)22
"جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھائے اور اگر روزے سےہو تو دعا کرے"
بعض علماء نے فرمایا:اس حدیث میں فلیصل سے مراد نماز ہے،پس وہ دعوت دینے والے کے گھر دو رکعت نماز پڑھے اور واپس آ جائے۔لیکن پہلا معنی دعا کرنا معروف ہے۔اور اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے۔جب حضرت اسماء ؓنے حضرت زبیرؓ کو جنم دیا تو حضرت اسماءؓ نے انہیں نبی کریمﷺ کی طرف بھیجا۔حضرت اسماءؓ نے فرمایا: (ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ)23(یعنی اس پر ہاتھ پھیرا اور انس کے لیے دعا کی)اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)24 (یعنی ان کے لیے دعا کیجیے)
اعشی نے کہا:
تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرُبْتُ مُرْتَحِلًا ... يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا
عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي ... نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا25
ان اشعار میں صلاۃ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔صحاح میں اس کا یہی معنی درج ہے۔26
بعض علماء نے کہا کہ یہ الصلا سے مشتق ہے ،اس سے مراد وہ رگ ہے جو پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے اور اس کے آخری حصے میں جدا ہو جاتی ہے اور اسے گھیر لیتی ہے۔اسی سے ہے "أُخِذَ الْمُصَلِّي فِي سَبَقِ الْخَيْلِ۔"27 مصلی گھوڑدوڑ میں شروع ہوا کیونکہ وہ دوڑ میں شریک ہوتا ہے اور اس کا سر سبقت لے جانے والےکے پچھلے حصہ کےقریب ہوتا ہے۔پس الصلا اس سے مشتق ہے یا پھر اس لیے کہ نماز کا ایمان کے بعد دوسرا نمبر ہے،پس نماز کو گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے یا اس لیے کہ رکوع کرنے والا اپنے پچھلے حصہ کو دوہرا کرتا ہے۔ الصلا گھوڑے کی دم کی جگہ کو کہتے ہیں۔اس کا تثنیہ صلوان ہے ۔المصلی ،دوسرے نمبر پر آنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا سر اگلے گھوڑے کے پچھلے حصے کے قریب ہوتا ہے۔28
بعض علماء نے کہا کہ یہ لزوم سے ماخوذ ہے اسی سے ہے صلی بالنار یعنی جب وہ آگ کو لازم ہوجائے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾29
حارث بن عباد نے کہا:لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا علم اللَّهـ ۔۔۔ وَإِنِّي بِحَرِّهَا الْيَوْمَ صَالِ30
اس شعر میں صال کا مطلب ہے کہ گرمی کو لازم پکڑنے والا ہے۔گویا اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حد پر عبادت کو لازم پکڑنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ صلیت العود بالنار سے ماخوذ ہے،جب تو لکڑی کو سیدھا کرے اور اسے آگ پر گرم کر کے اسے نرم کرے۔الصلاء، صلاءالنار صاد کے کسرہ کے ساتھ ممدود ہے اگر تو صاد پر فتحہ دے گا تو مقصورہ ہو گا گویا نمازی اپنے نفس کو عبادت میں لگا کر سیدھا کرتا ہے اور نرم کرتا ہے۔الخار زنجی نے کہا:
فَلَا تَعْجَلْ بِأَمْرِكَ وَاسْتَدِمْهُ ... فَمَا صَلَّى عَصَاكَ كَمُسْتَدِيمِ31
اس میں صلی سیدھا کرنے کے معنی میں ہے۔
الصلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے اسی سے ہے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ(اے اللہ محمدؐ پر رحمت بھیج)
الصلاۃ کا معنی عبادت بھی ہے اسی سے ہے ﴿وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾32 (یعنی ان کی عبادت بیت اللہ کے پاس نہ تھی)
الصلاۃ کامعنی نفلی نمازبھی ہےاسی معنی میں ہے: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾33 (اپنے گھر والوں کو نفلی نماز کا حکم دو) کا معنی قراءت بھی ہے۔اس معنی میں ہے: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾34 (اپنی قراءت کو بلند نہ کرو)
ابن فارس الصلوٰۃ کا لفظ اس مکان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔35
امام قرطبی بیان فرماتے ہیں :علماء اصول کا اختلاف ہے کہ کیا یہ اپنے اصل وضعی ابتدائی لغوی معنی پر باقی ہے۔اسی طرح ایمان ،زکوٰۃ،صیام اور حج (اپنے اصلی معنی پر باقی ہیں)شرع نے مشروط احکام کے ساتھ اس میں تصرف فرمایا۔یا شرع کی طرف سے یہ زیادتی اسے شرع سے پہلے کی وضع ابتدائی کی طرح موضوعہ کر دیتی ہے،یہاں بھی اختلاف ہے اور پہلا قول زیادہ صحیح ہےکیونکہ شریعت عربی زبان میں ثابت ہےاور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا لیکن عربوں کے لیے اسماء میں فیصلے کا اختیار ہے جیسے لفظ "دابتہ " ہر اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے جو زمین پر رینگ کر چلے پھر عرف نے اسے چوپائیوں کے لیے خاص کر دیا ،اسی طرح شرع کے عرف کے لیے اسماء میں انہیں اختیار ہے۔ واللہ اعلم ۔اس آیت میں صلوٰۃ کی مراد میں اختلاف ہے۔بعض علماء نے فرمایا:فرائض مراد ہیں،بعض نے فرمایا کہ فرائض و نوافل سب مراد ہیں۔ یہی صحیح ہے کیونکہ لفظ عالم ہے اور متقی فرائض و نوافل دونوں ادا کرتا ہے۔36
الذکر:
﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾ِ37
"اے آل یعقوب! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔"
اس آیت میں لفظ ذکر اسم مشترک ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں:"الذِّكْرُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ۔"38 ذکر بالقلب(دل کا ذکر)یہ بھولنے کی ضد ہے۔الذکر باللسان یہ خاموش رہنے کی ضد ہے۔"وَذَكَرْتُ الشَّيْءَ بِلِسَانِي وَقَلْبِي ذِكْرًا۔"(میں نے زبان اور دل سے اس کا ذکر کیا) وَاجْعَلْهُ مِنْكَ عَلَى ذُكْرٍ(بِضَمِّ الذَّالِ) (یعنی اس کو مت بھول)کسائی نے کہا کہ جو ذکر دل سے ہو وہ ذال کےضمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ذکر زبان کے ساتھ ہو وہ ذال مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔بعض دوسرے علماء نے کہا کہ یہ دونوں لغتیں ہیں۔کہا جاتا ہے: "ذِكْرٌ وَذُكْرٌ، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ۔"39
الذکر (بفتحہ ذال)مونث کا متضاد ہے۔الذکر کا معنی شرف بھی ہےاسی سے یہ ارشاد ہے: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾40
اسی طرح الماوردی نے بھی بیان فرمایا ہے:
"والذكر اسم مشترك, فالذكر بالقلب ضد النسيان, والذكر باللسان ضد الإنصات, والذكر الشرف۔"41
ابن انباری نےکہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میری نعمت کے شکر کو یاد کرو۔نعمت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے شکر کو حذف کیا گیا ہے۔بعض علما ءنے فرمایا کہ یہاں ذکر بالقلب مراد ہےاو روہی مطلوب ہے۔یعنی میری اس نعمت سے غافل نہ ہو جاؤ جو میں تم پر کی اور اسے بھول نہ جاؤ۔امام قرطبی فرماتے ہیں کہ "وَهُوَ حَسَنٌ"(یہ عمدہ قول ہے۔)42
قضی:
﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾43
"(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔"
ابن عرفہ نے کہا کہ قضاء الشی کا مطلب ہے اس کا احکام،اس کا جاری کرنا اور اس سے فارغ ہونا ہے۔اسی وجہ سے قاضی کو قاضی کہتے ہیں کیونکہ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو جھگڑاکرنے والوں کے جھگڑے سے فارغ ہو جاتا ہے۔الازھری نے کہا:لغت میں قضی کے کئی معنی ہیں۔اس کا مرجع کسی چیز کو ختم کرنا اور مکمل کرنا ہے۔ابو ذؤیب نے کہا:
وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا ... دَاوُدُ أَوْ صَنَعَ السَّوَابِغَ تُبَّعُ44
"ان کے اوپر دو زرہیں ہیں جنہیں داوؤد نے بنایا ہے یا تبع نے مکمل کی ہیں۔"
شماخ نے حضرت عمر بن خطابؓ کے بارے فرمایا:
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها ... بوائج في أكمامها لم تفتق45
یہاں پر بھی قضی کا معنی مکمل کے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ :
"قَالَ عُلَمَاؤُنَا:" قَضَى" لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ۔"46
کبھی یہ خلق کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے:
﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾47
"پس دو دن میں سات آسمان بنا دیئے۔"
کبھی یہ اعلام کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے:
﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾48
" اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے اپنی کتاب میں آگاہ کر دیا تھا۔"
کبھی یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾49
" اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔"
کبھی الزام اور احکام جاری کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾50" پھر جب موسٰی (علیہ السلام) نے مقررہ مدت پوری کر لی۔"
کبھی ارادہ کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا﴾51" جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔"
ابن عطیہنے کہا: "قَضى مَعْنَاهُ قَدَّرَ، وَقَدْ يجئ بِمَعْنَى أَمْضَى۔"52
قروء:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾53
"اور طلاق والی عور تیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں۔"
عربوں میں سے بعض قروء کا معنی حیض کرتے ہیں اور بعض طہر۔اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔اخفش کے نزدیک اس سے مراد حیض ہے۔جوہری قروء سے مراد طہر لیتے ہیں۔نحاس اس سے دونوں معنی یعنی طہر اور حیض مراد لیتے ہیں۔54
اہل کوفہ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں۔ان میں حضرت عمرؓ،علیؓ،ابن مسعودؓ، ابوموسیؓ،مجاہدؓ، قتادہؓ، ضحاکؓ، عکرمہؓ، سدیؓ،مالک،ابو حنیفہ اور اہل عراق شامل ہیں۔وہ اس شعر سے استشہاد فرماتے ہیں:
(يا رُبَّ ذي صغن عليّ فارض ... له قروءٌ كقروءِ الحائض)55
"یعنی اس نے اے نیزہ مارا تو اس کا خون حیض والی خاتون کی طرح تھا۔"
حضرت عائشہؓ،ابن عمرؓ،زید بن ثابتؓ،زھری،ابان بن عثمان،شافعی اور اہل حجاز قروء سے مراد طہر لیتے ہیں اور وہ اعشی کے اس شعر سے استشہاد فرماتے ہیں:
أفي كلِّ عامٍ أنتَ جَاشِمُ غزوةً ... تَشُدُّ لأقصاها عزِيمَ عزائِكَا
مُوَرّثَةً مالاً وفي الحيِّ رِفعَةٌ ... لِمَا ضاعَ فيها من قروءِ نِسائكا56
اور ایک قوم نے کہا کہ یہ" قروء" الماء فی الحوض سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد حوض میں پانی کا جمع ہونا ہے اور اسی سے القران ہے کیونکہ یہ معنی کو مجتمع ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجتماع حروف کی وجہ سے قرآن کہا جاتا ہےاور کہا جاتا ہے: مَا قَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ57
یعنی کبھی اس کے پیٹ میں جھلی جمع نہیں ہوئی اور عمرو بن کلثوم نے کہاہے:
ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءِ بِكْرٍ ... هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا58
تو گویارحم حیض کے وقت خون کو جمع کرتا ہے اور جسم طہر کے وقت اسے جمع کرتا ہے۔امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ القراء کا معنی الخروج ہے یعنی طہر سے حیض کی طرف اور حیض سے طہر کی طرف نکلنا ہے۔اسی بنا پر امام شافعی نے ایک قول میں کہ ہے:
"الْقُرْءُ الِانْتِقَالُ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ۔"59
"یعنی طہر سے حیض کی طرف انتقال۔"
وہ حیض سے طہر کی طرف انتقال نہیں کہتے۔اور اللہ تعالی کے اس ارشاد :
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾60
کا مطلب ہو گا تین ادوار یا تین انتقالات اور مطلقہ عورت صرف دو حالتوں سے متصف ہوتی ہے۔کبھی وہ طہر سے حیض کی طرف اور کبھی حیض سے طہر کی طرف اس کلام کا معنی صحیح ہو جائے گا اور اس کی دلالت طہر اور حیض دونوں پر ہو گی۔یہ اسم مشترک ہے۔61
المسیح:
﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾62
"جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالٰی تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔"
المسیح حضرت عیسی ؑکا لقب ہےاور اس کا معنی ہے صدیق ۔ قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. وَهُوَ فِيمَا يُقَالُ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ الشِّينُ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ63
ابن فارس نے کہا ہے:مسیح کا معنی پسینہ ہے اور المسیح کامعنی الصدیق ہے اور مسیح کا معنی ایسا درہم ہے جس پر نقش مٹا ہوا ہو۔المسح کا معنی جماع ہےکہا جاتا ہے: مَسَحَهَاوَالْأَمْسَحُ یعنی نرم و ملائم جگہ۔المسحا سے مراد وہ عورت جس کے کولہو اور ران کمزور ہوں۔المسائح انتہائی مضبوط عمدہ اونٹ،اس کی واحد مسیحۃ ہے
جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:
لَهَا مَسَائِحُ زُورٌ فِي مَرَاكِضِهَا ... لِينٌ وَلَيْسَ بِهَا وَهْنٌ وَلَا رَقَقُ64
اس شعر میں لفظ مسائح اسی معنی میں ذکر کیا گیاہے۔
ماوردی فرماتے ہیں:
وفي تسميته بالمسيح قولان: احدهما: لأنه مُسِحَ بالبركة , وهذا قول الحسن وسعيد. والثاني: أنه مُسِحَ بالتطهر من الذنوب۔65
مسیح ابن مریم کے بارے میں اختلاف ہےکہ وہ کون سے مادہ سے لیا گیا ہے؟پس کہا گیا ہے:لِأَنَّهُ مَسَحَ الْأَرْضَ66
کیونکہ آپ نے زمین میں خوب سیاحت کی اور اپنی حفاظت کے لیے گھر نہیں بنایا۔
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے:
كَانَ لَا يَمْسَحُ ذَا عَاهَةٍ إِلَّا بَرِئَ، فَكَأَنَّهُ سُمِّيَ مَسِيحًا لِذَلِكَ67
"کہ آپ جب کسی کوڑھ زادہ کو پھونک مارتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا ۔اسی لیے آپ کا نام مسیح پڑ گیا۔"
اس بنا پر فعیل بمعنی فاعل ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے:
"لِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ بِدُهْنِ الْبَرَكَةِ"68 "آُ پ کوبرکت والا تیل لگایا گیا ۔"
وہ تیل جو انبیاءؑ کو لگایا جاتا ہے ،وہ انتہائی خوشبو دار ہوتا ہے۔پس جب وہ لگایا جاتا ہے تومعلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ:
"لِأَنَّهُ كَانَ مَمْسُوحَ الْأَخْمَصَيْنِ۔"69 "ان کے دونوں پاؤں کے تلووں کو مس کیا گیا۔"
یہ بھی کہاگیا : "لِأَنَّ الْجَمَالَ مَسَحَهُ۔"70 "کیونکہ حسن و جمال نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا"
ایک قول یہ کیا گیا: "إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُسِحَ بِالطُّهْرِ۔"71
"ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے گناہوں سے پاک کر دیا تھا۔"
ابو الہیثم نے کہا: "الْمَسِيحُ ضِدُّ الْمَسِيخِ۔" (مسیح مسیخ کی ضد ہے۔)کہاجاتا ہے مسحہ اللہ(اللہ نے اسے انتہائی حسین اور مبارک پیدا فرمایا)اور مسخہ کا مطلب اللہ نے اسے انتہائی ملعون اور قبیح پیدا کیا۔ابن اعرابی نےکہا:"الْمَسِيحُ الصِّدِّيقُ"(مسیح کا معنی صدیق ہے)"وَالْمَسِيخُ الْأَعْوَرُ، وَبِهِ سُمِّيَ الدَّجَّالُ"(مسیخ کا معنی کانا،اور دجال کو یہی نام دیا گیا) شاعر کا اسی معنی میں قول ہے:"إن المسيح يقتل المسيخا" (بیشک مسیح ؑ دجال کو قتل کر دیں گے ) 72
رقیب:
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾73 "بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔"
ماوردی نے رقیب کے دو معنی بیان کیے ہیں:
أحدهما: حفيظاً , وهو قول مجاهد. والثاني: عليماً , وهو قول ابن زيد74
بعض کے نزدیک رقیب کے معنی حفاظت کرنے والا،انتظار کرنے والا ہے۔المرقب بلند و بالا جگہ کو کہتے ہیں جس پر رقیب کھڑا ہوتا ہے۔الرقیب سات تیروں میں سے تیسرے تیر کو کہتے ہیں۔یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رقیب سانپوں میں سے ایک سانپ ہے۔پس یہ لفظ مشترک ہے۔75
موالی:
﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾76
"اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو (حقداروں میں تو تقسیم کر دو کہ) ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں۔"
"أَنَّ الْمَوْلَى لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ۔"77
موالی کا لفظ مشترک ہے اور یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے:آزاد کرنے والا،آزاد کیا گیا،آزاد کرنے والے کو مولیٰ اعلیٰ اور آزاد کیے گئے کو مولی اسفل کہتے ہیں۔78
مددگار کو بھی مولی کہتے ہیں:
﴿ وَأَنَّ الْكافِرِينَ لَا مَوْلى لَهُمْ﴾79
چچا کے بیٹے کو مولی کہا جاتا ہے۔ پڑوسی کو بھی مولی کہا جاتا ہے۔80
مسح:
﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾81
"سو تم (اس پر دونوں ہاتھ مار کر) مسح کر لو، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بیشک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت ہی بخشنے والا ہے۔"
الْمَسْحُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يَكُونُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ82
مسح لفظ مشترک ہیں اس کا معنی اجماع ہے۔کہا جاتا ہے: مَسَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ83(مرد نے عورت سے جماع کیا)
والمسح: مسح الشيء بالسيف(مسح مطلب چیز کو تلوار سے کاٹا)
وَمَسَحَتِ الْإِبِلُ يَوْمَهَا(اونٹ پورا دن چلا)
والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا إست لها(المسحا ایسی عورت جس کے سیرین نہ ہوں)
یہاں مسح سے مراد ممسوح چیز پر ہاتھ کو کھینچنا،اگر وہ آلہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد آلہ کو ہاتھ کی طرف نقل کرنا ہے۔84
حجر:
﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾85
"اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ۔"
امام طبری نے الحجر کی تین لغات بیان کی ہیں: "حجر" بكسر الحاء، والجيم قبل الراء"وحُجر" بضم الحاء، والجيم قبل الراءو"حِرْج"، بكسر الحاء، والراء قبل الجيم.86
و"الحِجْر" في كلام العرب، الحرام.ملتمس کا قول ہے:
حَنَّتْ إلَى النَّخْلَةِ القُصْوَى فَقُلْتُ لَهَا: ... حِجْرٌ حَرَامٌ، أَلا ثَمَّ الدَّهَارِيسُ87
وَالْحِجْرُ: لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ. وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْحَرَامِ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ88
الحجر لفظ مشترک ہے،یہاں اس کا معنی حرام ہے اصل میں اس کا معنی روکنا ہےاور عقل کو حجر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ برائیوں سے روکتی ہےحجر مونث گھوڑے کو بھی کہا گیا ہےاور حجر کا معنی قرابت بھی ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے:
يُرِيدُونَ أَنْ يُقْصُوهُ عَنِّي وَإِنَّهُ ... لَذُو حَسَبٍ دَانٍ إِلَيَّ وَذُو حِجْرٍ89
فرش:
﴿وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۭكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭاِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾90
"اور بوجھ اٹھانے والے مویشی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔"
فرش سے مراد وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہےاور دودھ پیا جاتا ہے،جیسا کہ بکریاں اونٹوں کے بچے اور گائیوں کے بچھڑے وغیرہ ۔ان کے اجسام کی لطافت اور ان کے فرش کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کا نام فرش رکھا گیا۔اور فرش سے مراد ایسی ہموار جگہ جس پر لوگ آسانی سے چل سکتے ہیں۔راجز نے کہا:
أورثني حمولة وفرشا ... أمشّها في كل يوم مشّا91
الفرش سے مراد گھر کا وہ سازوسامان جو بکھیر دیا گیا ہو اور فرش سے مراد وہ کھیتی بھی ہے جب وہ پھیل جائے اور فرش کا معنی وسیع فضابھی ہے۔ فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ92
نحاس نےکہا: الفرش:ما خلقه الله عزّ وجلّ من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهّد93 (فرش وہ ہے جسے اللہ تعالی نے ایسی جلد اور اون کے ساتھ پیدا کیا ہو جس پر بیٹھا جاسکتا ہو اور اسے بچھایا جاسکتا ہو)
العرش:
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾94
"کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا ۔ پھر عرش پر ٹھہرا۔"
(عَلَى الْعَرْشِ) لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ95
علی العرش یہ لفظ مشترک ہے،ایک سے زیادہ معنی پر اطلاق ہوتا ہے۔
ابی معالی کے نزدیک العرش کا معنی: الملك، والسلطان96
وكل سقف عند العرب هو عرش97
اھل عرب کے نزدیک ہر چیز کی چھت عرش کہلاتی ہے۔اسی میں اللہ باری تعالی کا ارشاد ہے:
﴿خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾98
علامہ جوہری وغیرہ نے کہا کہ : الْعَرْشُ سَرِيرُ الْمُلْكِ99 (بادشاہ کا تخت)
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿نَكِّرُوا لَها عَرْشَها﴾100(شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی)
﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾101(اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا)
وَعَرْشُ الْقَدَمِ: مَا نَتَأَ فِي ظَهْرِهَا وَفِيهِ الْأَصَابِعُ.102(قدم کی پشت کا بلند حصہ اور اس میں انگلیاں بھی ہیں)
عرش السماک(چار چھوٹےستارےجو عواء (چاند کی منازل میں سے ایک منزل)کے نیچے ہیں)،عرش اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جو بلند عمارت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔عرش مکہ مکرمہ کا نام بھی ہے۔عرش کا معنی ملک اور سلطنت بھی ہے۔زہیر نے کہا:
تَدَارَكْتُمَا عَبْسًا وَقَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا ... وَذُبْيَانُ إِذْ ذَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ103
الأمة:
﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾104
"اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔"
ابن عباسؓ ومجاهد وقتادة وجمہور مفسرين کے نزدیک امۃ کا مفہوم یہ ہے:
وتكون الأمة عبارة عن المدة،واصلها الجماعة105
امام قرطبی فرماتے ہیں:"وَالْأُمَّةُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ يُقَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ۔"106
"امت کا لفظ مشترک ہے اور اس کی آٹھ صورتیں بنتی ہیں۔"
1۔امت جماعت کے معنی میں ہے: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ﴾107
2۔امت سے مراد بھلائی کا وہ جامع آدمی ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:﴿إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً﴾108
3۔امت سے مراد دین اور ملت ہے۔جس طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے:﴿إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ﴾109
4۔امت سے مراد حین اور زمان ہے: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾110
5۔امت سے مراد قد و قامت ہے۔اس سے مراد انسان کی لمبائی اور اس کی بلندی ہے۔اسی سے کہا جاتا ہے:"فلان حسن الامۃ" (فلاں اچھی قامت والا ہے)۔
6۔امت سے مراد ماں ہے۔کہاجاتا ہے هَذِهِ أُمَّةُ زَيْدٍ(یعنی زید کی ماں)
7۔امت سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے دین میں منفرد ہواس میں کوئی بھی اس کا شریک نہ ہونبی کریمﷺ نے فرمایا:(يُبْعَثُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أُمَّةً وَحْدَهُ۔)
8۔امت انبیاء کے پیروکاروں کو بھی کہتے ہیں۔
خلاصہ بحث:
حاصل یہ ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو ااس لیے اس میں مترادفات،مشترک الفاظ او ر اضداد کا وجود پایا جاتا ہےجس کی بنا پر ائمہ مفسرین،فقہا اور متکلمین میں قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر و تاویل اور تشریح و توضیح بیان کرنے میں تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے۔یعنی جب کوئی لفظ مختلف وجوہ اور معنی رکھتا ہے تو مفسرین کے لیے پنے اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق اس لفظ کے معنی بیان کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔اس قسم کے معنی قرآن مجید میں وسعت کا باعث بنتے ہیں۔
حواشی و حوالہ جات
۔ الْيَازِجِيّ، إبراهيم بن ناصف بن عبد الله ، نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد،مطبعة المعارف، مصر،1905ء،ج1،ص1
Alyāzjī,Ibrāhēm bin Abdullah,Njāt ul rāid wa Shir'at ul wārid fi Almutrādaf wa Almutwārad,Al'Matba Al'ma'āraf ,Miser,1905,V.1,pg.1
2۔ سیوطی،جلال الدین،علامہ،الاتقان فی علوم القرآن،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة الكتاب1974ء ج2،ص147۔148
Sayūti,Jalāl-o-dēn,Allāma,Al-Itteqān fī Alūm-ul-Qurān,almuhaqqaq:Muhammad Abū Al-Fazal Ibrāhēm,Al-hayyāh Al-misryah Al'āmat-ul-kitāb,1974,V.2,pg.147-148
3۔سورۃ الفاتحہ4:1
Sūrāh Al-fātiha1:4
4۔ القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين،أبوعبد الله، الجامع لأحكام القرآن،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،دار الكتب المصرية - القاهرة ،1964م،ج1،ص144
5Al-Qartabi,Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah,Abu Abdullah,Aljamio Le-Ahkām-ul-Qurān,Tahqiq:Ahmad Al'bardūni wa Ibrāhēm Atfēsh,Dār-ul-kutab,Almisrya,Alqāhira,1964,V.1,pg.144
۔سورۃ النور٫25:24
6Sūrāh Al-Nūr 24:25
۔سورۃ غافر17:40٫
7Sūrāh Gāfer 40:17
۔سورۃ الجاثیہ28:٫45
8Sūrāh Al-jāsiya 45:28
۔سورۃالصافات52:37٫
9Sūrāh Al-Suāfāt 37:52
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص1٫44
10Tafsēr Qartbi,V.1,pg.144
۔ایضاً
11Ibid
۔ ایضاً
Ibid
12 ۔ ایضاً
Ibid
13 ۔ الماوردي،علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،أبو الحسن،النکت والعیون،المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ج1،ص57٫
14Al-Māwardi,Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al'basri Al-Baqdādi,Abu Al-Hassan, Al-Nukatu wa Al'Oyoūn,Al'muhaqiq:Sayad bin Abd-ul-Maqsūd bin Abd-ul-Rāhēm,Dar-ul-kutab Al'ilmiyah,Bērūt,Labnān,V.1,pg.57
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص144
15Tafsēr Qartabi,V.1,pg.144
۔ایضاً
16Ibid
۔ایضاً
Ibid
17۔ایضاً
Ibid
18۔تفسیر قرطبی،ج1،ص145
19Tafsēr Qartabi,V.1,pg145
۔ایضاً
20Ibid
۔سورۃالبقرۃ3:2
21Sūrāh Al-Baqarah 2:3
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص169
22Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169
۔ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،صحیح مسلم، المحقق:محمد فؤادعبد الباقي،دار إحياء التراث العربي - بيروت بَابُ :الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ،ح1431،ج2،ص1054
23Muslim bin Hajāj,Abu Al-Hassan Al-Qashērī,Sahīh Muslim,Almuhaqaq:Fawād Abd-ul-Baqi,Dār Ahyā au-ttrās Alarbi,Bērūt,Bāb:Al-Amro bejābāt addāī īlā .i.dāwāh,Hadēs:1431,V.2,pg.1054
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص168
24Tafsēr Qartabi,V.1,pg.168
۔سورۃالتوبۃ103:9
25Sūrāh Tūbah 9:103
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص168
26Tafsēr Qartabi,V.1,pg.168
۔ایضاً
27Ibid
۔ایضاً
28Ibid
۔ایضاً
Ibid
29 ۔سورۃالغاشیۃ4:88
Sūraāh Al-Gāshīyāh88:4
30۔تفسیر قرطبی،ج1،ص169
31Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169
۔ایضاً
32Ibid
۔سورۃالانفال35:8
33Sūrāh Al-Infāl 8:35
۔سورۃطہ132:20
34Sūrāh Tāhā 20:132
34۔سورۃالسراء110:17
35Sūrāh Al-Isrā 17:110
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص169
36Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص169۔170
37Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169-70
۔سورۃ البقرۃ40:2
38Sūrāh Al-Baqarā 2:40
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص331
39Tafsēr Qartabi,V.1,pg.331
۔النکت والعیون ،ج1،ص111
40Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.111
۔سورۃزخرف44:43
41Sūrāh Zukhruf 43:44
۔ النکت والعیون ،ج1،ص111
42Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.111
۔تفسیر قرطبی،ج1،ص331
43Tafsēr Qartabi,V.1,pg.331
۔سورۃالبقرۃ117:2
44Sūrāh Al-Baqarā 2:117
۔النکت والعیون،ج1،ص178
45Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.178
۔ایضاً
46Ibid
۔تفسیر قرطبی،ج2،ص88
47Tafsēr Qartabi,V.2,pg.88
۔سورۃ فصلت12:41
48Sūrāh Fussilāt 41:12
۔سورۃ الاسراء4:17
49Sūrāh Al-Isrā 17:4
۔سورۃ الاسراء23:17
50Sūrāh Al-Isrā 17:23
۔سورۃالقصص29:28
51Sūrāh Al-Qasas 28:29
۔سورۃ البقرۃ117:2
52Sūrāh Al-Baqarā 2:117
۔تفسیر قرطبی،ج2،ص88
53Tafsēr Qartabi,V.2,pg.88
۔سورۃ البقرۃ228:2
54Sūrāh Al-Baqarā 2:228
۔تفسیر قرطبی،ج2،ص112
55Tafsēr Qartabi,V.2,pg.112
۔النکت والعیون،ج1،ص291
56Al'nukatu wa al'Oyoūn,V.1,pg.291
۔ النکت والعیون،ج1،ص291
57Al'nukatu wa al'Oyoūn,V.1,pg.291
۔ تفسیر قرطبی،ج3،ص114
58Tafsēr Qartabi,V.3,pg.
۔ایضاً
59Ibid
۔ایضاً
60Ibid
۔سورۃ البقرۃ228:2
61Sūrāh Al-Baqarā 2:228
۔تفسیر قرطبی،ج3،ص114
Tafsēr Qartabi,V.3,pg.114
62 سورۃآل عمران45:3
63Sūrāh Al-Imrān 3:45
۔تفسیر قرطبی،ج4،ص88
64Tafsēr Qartabi,V.4,pg.88
۔تفسیر قرطبی،ج4،ص89
Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89
65۔النکت والعیون،ج1،ص394
66Al'nukatu wa Al'Oyoūn,V.1,pg.394
۔تفسیر قرطبی،ج4،ص89
Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89
67 ۔ایضاً
68Ibid
۔ایضاً
69Ibid
ٰ ۔ایضاً
70Ibid
۔تفسیر قرطبی،ج4،ص89
71Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89
۔ ایضاً
72Ibid
۔ایضاً
73Ibid
۔سورۃ النساء1:4
74Sūrāh Al-Nisā 4:1
۔النکت والعیون،ج1،ص447
75Al'nukatu wa al'Oyoūn,V.1,pg.447
۔تفسیر قرطبی،ج5،ص8
76Tafsēr Qartabi,V.5,pg.8
۔سورۃ النساء33:4
77Sūrāh Al-Nisā 4:33
۔تفسیر قرطبی،ج5،ص166
78Tafseer Qartabi,V.5,pg.166
۔ایضاً
79Ibid
۔سورۃ محمد11:47
80Sūrāh Muhammad 47:11
۔تفسیر قرطبی،ج5،ص167
81Tafsēr Qartabi,V.5,pg.167
۔سورۃالنساء43:4
82Sūrāh Al-Nisā 4:43
۔تفسیر قرطبی،ج5ص238
83Tafsēr Qartabi,V.5,pg.238
۔ایضاً
84Ibid
۔تفسیر قرطبی،ج5،ص239
85Tafsēr Qartabi,V.5,pg.239
۔سورۃالانعام138:6
Sūrāh Al-Anām6:138
86۔الطبري،أبو جعفر،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن،المحقق: أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة،2000ء،ج12،ص142
87Al-Tabri,Abu Jāfer,Muammad bin Jarir bin Yazēd bin Kasēr,Jame-ul-Biān fi Tāwēl-Ul-Qurān,Muhaqaq:Ahmad Muhammad Shākir,moasasāto rsālāh,2000,V.12,pg.142
تفسیر طبری،ج12،ص140
88Tafsēr Tabri,V.12,pg.140
تفسیر قرطبی،ج7،ص94
89Tafsēr Qartabi,V.7,pg.94
۔ایضاً
90Ibid
۔سورۃالانعام142:6
91Sūrāh Al-Anām6:142
۔النکت والعیون،ج2،ص179
92Al'nukatu wa Al'Oyoūn,V.2,pg.179
۔تفسیر قرطبی،ج7،ص112
Tafsēr Qartabi,V.7,pg.112
93 ۔النَّحَّاس،أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي،أبو جعفر،اعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ،1421 ھ،ج2،ص35
94Al.Nahās,Ahmad bīn Mūhammad bīn Ismāēl bīn Yoūnas Al-mrādī Al-Nahv,Abū Jāfer,I'rab Ul-Qurān,Waz'ā Hwāshiā Wa ā'lqā ā'lēhī,Abūlmūnam Khalēl Ibrāhēm,Manshūrāt Mūhammad Alī BīZūn,Dār Ul-Kūtab Al-Ilmiyā,Bērūt,1421,V.2,pg.35
۔سورۃالاعراف54:7
95Sūrāh Al.Airāf 7:54
۔تفسیر قرطبی،ج7،ص220
96Tafsēr Qartabī,V.7,pg.220
۔الثعالبی،عبدلرحمن بن محمد،ابو زید، الجواهر الحسان في تفسير القرآن،المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،دار إحياء التراث العربي – بيروت،1418ھ،ج3،ص37
97Al-Sālbī,Abdurahmān bin Muhammad,Abu Zaid,Al-Jwāher-ul-Ihsān fī Tafsēr ul-Qurān,Almohaqaq:Shaikh Muhammad Alī Ma'uwaz,Shaikh Adil Ahmad Abd-ul-Mojūd,Dār Ahyā-au-Trās Alarbī,Bērūt,1418,V.3,pg.37
۔النکت والعیون،ج2،ص230
98Al'nukatu wa Al'Oyoūn,V.2,pg.230
۔سورۃالکہف42:18
99Sūrāh Al-Kehf 18:42
۔تفسیر قرطبی،ج7،ص220
100Tafsēr Qartbi,V.7,pg.220
۔سورۃالنمل41:27
101Sūrāh Al-Naml 27:41
۔سورۃ یوسف100:12
102Sūrāh Yoūsaf 12:100
تفسیر قرطبی،ج7،ص220
103Tafsēr Qartbi,V.7,pg.220
۔ایضاً
104Ibid
۔سورۃ ھود8:11
105Sūrāh Hūd 11:8
۔النکت والعیون،ج2،ص460،تفسیر قرطبی،ج9،ص9
106Al'nukatu wa Al'Oyoūn,V.2,pg.460, Tafsēr Qartbi,V.9,pg.9
۔تفسیر قرطبی،ج9،ص10
107Tafsēr Qartbi,V.9,pg.10
۔سورۃ القصص23:28
108Sūrāh Al-Qasas 28:23
۔سورۃ النحل120:16
109Sūrāh Al- Nahal 16:120
۔سورۃ زخرف22:43
110Sūrāh Al- Zukhruf 43:22
سورۃ یوسف45:12
Sūrāh Yoūsaf 12:45
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |