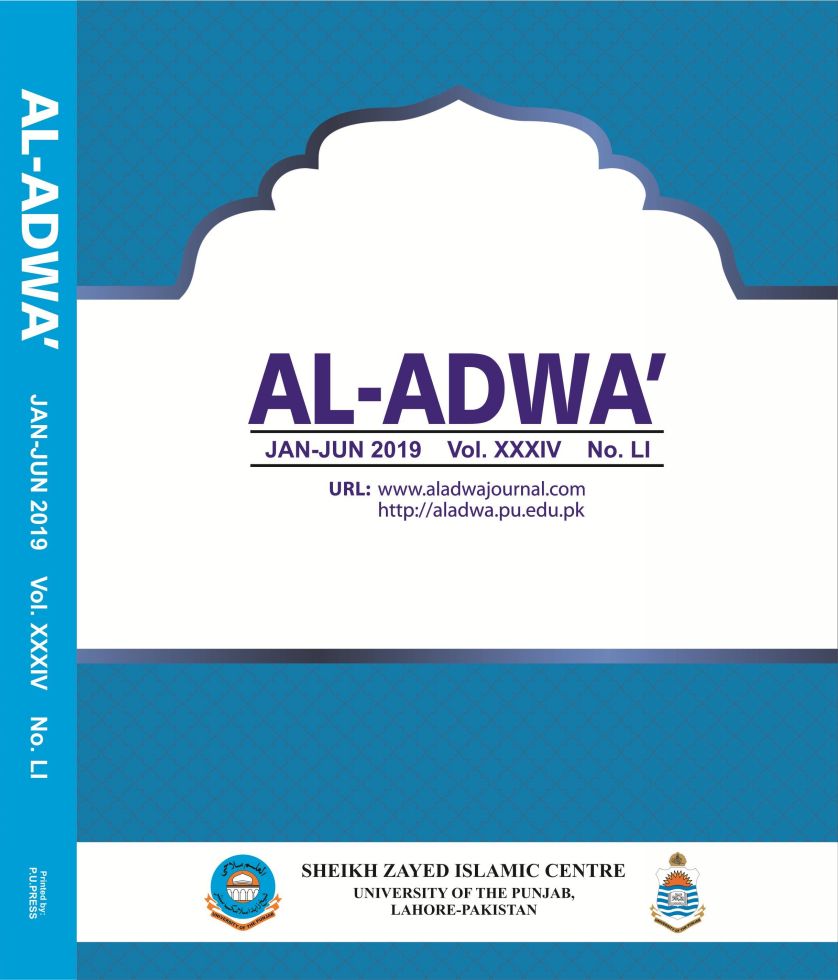37
57
2022
1682060078052_3032
71-96
https://journal.aladwajournal.com/index.php/aladwa/article/download/4/373
https://journal.aladwajournal.com/index.php/aladwa/article/view/4
Economic Nature Capitalism Socialism Islamic Economic System Applied Features of Social Justice
عدل اجتماعی کا نظریہ اسلامی عدل کو وسیع اور جامع انسانی عدل کے طور پر پیش کرتا ہے جو کہ صرف مادی امور یا معاشی مسائل تک محدود نہیں، اس کے نزدیک زندگی کی قدریں بہ یک وقت مادی بھی ہیں اور معنوی بھی، دونوں میں تفریق کرنا صحیح نہیں انسانیت ایک جامع وحدت ہے، جس کے مختلف عناصر باہم مربوط و ہم آہنگ اور ذمہ داریوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔عدل اجتماعی تین بنیادی اصولوں پہ مبنی ہے: ۱۔مطلق اور مکمل آذادی ضمیر،۲۔کامل انسانی مساوات، ۳۔ٹھوس اور پائیدار اجتماعی تکافل۔پہلے اصول کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو غیر اللہ کی عبادت اور اطاعت و فرماں برداری سے آزاد کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو ا نسان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔لوگوں کی عزت و آبرو اور ان کے شرف و جاہ کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔اس میں خود داری اور عزتِ نفس پرورش پائے اور وہ عدل و انصاف کے قیام کے نگران و محافظ بن کر رہیں۔ دوسرے اصول کے مطابق انسانوں میں مساوات کو یقینی بناتا ہے اور بغیر کسی تفریق کے سب کے لئے ایسا ماحول بناتا ہے جس میں انسان اپنی جان، پیٹ بھرنے کے لئے غذا اور زندگی میں اپنی حیثیت ان تمام کے سلسلے میں ہر طرح کے خوف سے آزاد رہے اور سب کی ایسی اخلاقی تربیت کی جائے کہ جس میں کوئی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے،اس طرح قانون کے علاوہ ان باتوں کے ذریعے بھی وہ ایک مکمل اور ایک مطلق عدل اجتماعی کے قیام کی ضمانت دے۔تیسرے اصول کے مطابق فر د اور معاشرے کے باہم حقوق طے کرتا ہے انسان مدنی الطبع ہے یعنی فطری طور پہ اجتماعیت پسند ہے اُنس اور مل جل کر زندگی بسر کرنا اس کا فطری تقاضا ہے اس ضِمن میں یہ اصول نہ تو فرد کو بے لگام چھوڑتا ہے اور نہ ہی معاشرے کو اس کی انفرادیت کچلنے کی تحریک دیتا ہے بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک ایسا راستہ پیش کرتاہے کہ جس میں انفرادی آذادی کے بالمقابل انفرادی ذمہ داری کا اصول پیش کرتا ہے اور اس کے پہلو میں اجتماعی ذمہ داری کو جگہ دیتا ہے جس کا بار فرد اور جماعت دونوں پر ہے ذمہ داریوں کا یہ اشتراک ایک کامیاب نظام معاشرت کی بنیاد رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکہ اور احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں عدل اجتماعی کے تناظر میں اسلامی نظام معیشت کے بنیادی تخصّصات درج ذیل ہیں۔
معاشی نوعیت :
معاشیات کے معنی ہیں روٹی سے متعلق مسائل۔عیش روٹی (گندم) کو کہتے ہیں۔عربی لغت میں قصد اور اقتصاد میانہ روی اور اچھے چلن کا نام ہے لیکن اصطلاحی لحاظ سے انسان کی ضروریات و احتیاجات کو پورا کرنے کے لئے محنت و سعی اور تعاون اور اشتراک سے ذرائع پیداوار تلاش کرنے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا نام ہے۔اور اگر اسلام کی رُو سے معاشیات کی تعریف کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے :"علم معاشیات زندگی کا وہ مالی شعبہ ہے جو قرآن اور حدیث کی ہدایت کے مطابق فلاح و بہبود انسانی کے لئے منضبط ہوتا ہے "[i]
علم الاقتصاد اجتماعی زندگی کی اصل بنیاد ہے اور انسانی زندگی کے ہر دور میں معاشی مسئلہ کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے جس کے حل کرنے کے لئے مختلف قسم کی تحریکیں اٹھی ہیں۔ان میں سے اجتماعیت، کمیونزم، سوشلزم، فاشزم اور سرمایہ داری خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ تحریکات مختلف نظریات کے نتائج میں آئیں سب سے پہلے افلاطون نے اپنی مشہور کتاب ری پبلک (republic)میں معاشی نظریہ پیش کیا۔پھر ارسطو، ترگاٹ، آدم سمتھ، ہیگل اور کارل مارکس کے نظریات نے علم اقتصاد کی ترویج کے لئے کام کیا اس طرح اہل مغرب نے اقتصاد کے شعبے میں بہت سے نظریات دیئے جن سے کچھ نظاموں نے جنم لیا ان میں سے چند نظریات نے بہت شہرت حاصل کی جدید مفکرین میں سے کارل مارکس کے نظریہ اشتراکیت نے یورپ اور روس میں انقلاب برپا کیا۔آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں دو قسم کا نظام معیشت رائج ہے ایک کیپیٹل ازم یا سرمایہ دارانہ نظام ا ور دوسرا کمیونزم یا سوشلزم ہے یہاں ان دونوں نظاموں کا مخنتصر سا جائزہ پیش ہے تاکہ اسلامی نظام معیشت کی اکملیت اور برتری ان نظاموں پر ثابت کی جا سکے۔
کیپیٹل ازم یا سرمایہ داری :
سرمایہ داری نے جاگیر داری سے جنم لیا تھا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اسلام سے پہلے بھی تمام ترقی یافتہ سلطنتوں میں سرمایہ داری نظام رائج تھا جب اس نظام کے بد اثرات عوام پر پڑنے لگے تو وہ سلطنتیں ان بد اثرات کی وجہ سے مٹ گئیں اس کی جگہ اسلام کا صالح نظام وجود میں آگیا۔ولیم این لوکس (Welliam N.Loucks)نے اس نظام کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے :
"Capitalism is a system of economic organization in which individual person singly in groups privately owned production resources, including land and possess the right to use these resources generally in whatever manner they choose." [ii]
"سرمایہ دارانہ نظام سے مراد وہ معاشی نظام ہے جس میں افراد کو ذاتی ملکیت کے حقوق حاصل ہوتے ہیں سرمایہ کاری اور پیداوار کے متعلق فیصلے بھی افراد نجی طور پر کرتے ہیں اور اشیاء و خدمات کی پیداوار اور ان کی بازار میں فراہمی منافع کی خاطر کی جاتی ہے اس نظام کے تحت اشیاء و خدمات کی قیمتوں کا تعین ان کی طلب اور رسد کے باہمی آزادانہ عمل اور ردعمل سے ہوتا ہے۔"
سرمایہ داری نظام کی خصوصیات:
اس نظام کی چند بنیادی خصوصیات درج ذیل ہیں۔
1: ذاتی یا نجی ملکیت:
اس نظام کے تحت ہر شخص کو ذاتی ملکیت کا حق حاصل ہو تا ہے تمام وسائل پیدائش نجی ملکیت میں ہوتے ہیں حکومت ان وسائل کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے لوگوں کو جائیداد بنانے، اسے بیچنے اور وارثین کو منتقل کرنے کی اجازت ہوتی ہے نجی ملکیت کا حق غیر محدود ہے۔
2: معاشی آزادی :
اس نظام میں ہر شخص اپنی املاک کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اسے پیشے کے انتخاب میں بھی آزادی ہوتی ہے لوگ عموماََ اپنے انفرادی اور شخصی فائدے کی خاطر جدوجہد کرتے ہیں انھیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی اس طرح قومی آمدنی کا بیشتر حصہ سرمایہ داروں اور زمینداروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔مزدور کو اس کی محنت و کاوش کا صلہ نہیں ملتا اوران کا استحصال ہوتا ہے۔معاشی آزادی کی وجہ سے ہر فرد صَرف اور پیدائش دولت کے متعلق آزادانہ فیصلے کرتا ہے تمام کاروباری ادارے طریق پیدائش اور پیمانہ پیدائش کا خود فیصلہ کرتے ہیں۔عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم اپنی خدمات کی فروختگی یا انھیں کرایہ پر دینے کے متعلق خود فیصلے کرتے ہیں۔ اس نظام کے تحت صارف کی حیثیت ایک مطلق العنان حاکم کی طرح ہے آجر اسی کی پسند اور ناپسند کو پیش نظر رکھتا ہے اگر وہ اس کی پسند کا خیال نہ کرے تو اسے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔[iii]
3: طبقاتی کشمکش :
اس نظام کی بڑی خصوصیت دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔امیر بہت امیر ہوتے ہیں جنھیں زندگی کا ہر عیش میسر ہوتا ہے جبکہ غریب بہت غریب ہوتے ہیں جو نان و نفقہ کے محتاج ہوتے ہیں اس سے معاشرہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے امیر افراد وسائل پیدائش کے مالک ہوتے ہیں ان کے قبضے میں بڑے بڑے کارخانے اور وسیع زمینیں ہوتی ہیں ملکی دولت کا ذیادہ حصہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے اور انھیں ترقی کے تمام مواقع میسر ہوتے ہیں جبکہ غریب ان سے یکسر محروم ہوتا ہے طبقاتی کشمکش اس نظام کا حصہ ہے جس کے نتیجے میں آجر و اجیر، زمیندار و مزارع، صنعتی مزدور و مالکان وغیرہ کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اور بہت سی حقوق کی تنظیموں کا وجود عمل میں آیا جن سے بہتری کی بجائے بہت سے معاشرتی مسائل میں اضافہ ہوا۔
4: تقسیم کار :
پیدائش دولت تخصیص کار کے اصولوں پر ہوتی ہے یہ اصول ہر معاشی نظام میں کارفرما ہوتے ہیں اشتراکیت میں تقسیم کار میں لوگوں کی پسند کا کوئی دخل نہیں ہوتا جبکہ سرمایہ داری نظام میں لوگوں کی پسند اہم کردار ادا کرتی ہے اور باہمی مبادات اور منڈی کے تقاضوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہے۔البتہ لوگ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں اور بعد میں جب منڈی کی وسعت کی وجہ سے پیدائش دولت وسیع ہو جاتی ہے تو تقسیم کار بھی سادہ سے پیچیدہ ہو جاتا ہے ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اشیاء بناتا ہے اور منڈی میں اسے فروخت کرکے اپنی ضرورت کی دوسروں کی پیدا کی ہوئی چیزیں خرید لیتا ہے۔
5: قیمتوں میں میکانیت :
یہ نظام قیمتوں کی میکانیت کی وجہ سے چلتا ہے اس کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا کوئی پیشہ یا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہر فرد کے پیش نظر منافع ہوتا ہے منافع لاگت اور قیمت میں فرق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔طریق پیدائش میں ردو بدل نہ ہونے کی وجہ سے مصارف پیدائش تو عرصہ قلیل میں یکساں رہتے ہیں مگر قیمت میں تغیّرو تبدل ہوتا ہے جن سے منافع کی شرح بھی متاثر ہوتی ہے۔کسی شے کی قیمت چڑھنے میں طلب اور رسد دونوں اثر انداز ہوتے ہیں طلب بڑھنے یا رسد کم ہونے سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔قیمتوں کی میکانیت سے آجرین بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں آجر ہمیشہ اسی سے رسد فراہم کرے گا جس کی قیمت زیادہ ہو گی۔
6: آزاد مقابلہ :
یعنی تمام اشیاء کی خرید وفروخت آزادانہ طریق پر ہوتی ہے گاہک اپنی مرضی کے مطابق منڈی سے چیزیں خریدتے ہیں اور فروخت کار اپنا منافع بڑھانے کے لئے گاہکوں کو مختلف طریقوں سے اپنی جانب کھینچتے ہیں اس طرح طلب اور رسد کی دونوں متضاد قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوتی ہیں۔ زمین کی ہر اکائی دوسری اکائی کے ساتھ مختلف استعمالات کے لئے مقابلہ کرتی ہے اور اسی طرح سرمایہ کی ہر اکائی بھی دوسری اکائی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔[iv]
7: کساد بازاری اور بے روزگاری :
بچت اور سرمایہ کاری، صرف اور پیدائش دولت میں عدم مطابقت کی وجہ سے سرمایہ داری نظام اکثر اوقات معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے اشیاء کی قیمتیں گر جاتی ہیں قیمتیں گرنے سے منافع کم ہوتا ہے جس سے پیمانہ پیدائش محدود ہوجاتاہے یوں بہت سے مزدور کام سے نکال دیئے جاتے ہیں یہ بے روزگاری مجموعی قوت خرید کو گھٹا کر معیشت کو کساد بازاری کا شکار بنا دیتی ہے۔
8: آجر کی اہمیت :
آجر اس نظام کا مرکزی کردار ہے۔پیداواری زرائع اس کی ہدایت کے تحت کام کرتے ہیں وہی عوامل پیدائش کو استعمال کر کے مادی وسائل کو بروئے کار لاتا ہے پیدائش کے معاملے میں وہ تنہا معاشرے کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے وہ کاروبار کی ابتداء اور انتظام ہی نہیں کرتا بلکہ احتمال نقصان بھی برداشت کرتا ہے تشکیل سرمایہ کا وہی سب سے بڑا منبع ہے۔ اور دوسری طرف صارف ہوتا ہے وہ ترجیحات کے ذریعے احکامات صادر کرتا ہے اگر آجر کی توقعات اور اندازے غلط ہو جائیں اور وہ صارف کی خواہشات کو بالکل ہی نظر انداز کر دے تو صارف کا ردعمل آجر کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اجارہ داریوں کی وجہ سے بھی صارف کی برتری پر زد پڑتی ہے اجارہ دار کی حیثیت ایک عام آجر کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔الغرض اگر اس نظام کی مجموعی طور پہ بات کی جائے تو سرمایہ داری نظام ایک بے لگام اور لامحدود انفرادی ملکیت کا حامل ہے جس میں سود، احتکار اور اکتناز شامل ہیں اس نظام میں نسلی اور جغرافیائی امتیازات ضروری ہیں سرمایہ دار کو اپنے مفاد کے علاوہ دوسروں کی ضروریات اور مفادات سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ دوسروں کو زیرِ دست رکھنا پسند کرتے ہیں۔گذشتہ ادوار کے سرمایہ دارانہ نظام نے انفرادی غلامی کو فروغ دیا دور حاضر میں آزاد اور خود مختار ممالک کی اقتصادیات کو اپنے قبضے میں لے کر بلواسطہ غلامی کا جوا ان کو پہنا دیا ہے گویا خود مختار ملک کہلانے والے بھی سرمایہ دار ممالک کے غلام ہیں اس سے صاف ظاہر ہے سرمایہ دار نظام اپنے اندر دوسروں کو غلام بنانے کی لعنت لئے ہوئے ہے۔ [v]
کمیونزم/ سوشلزم :
جب یورپ جاگیر داری نظام سے سرمایہ داری نظام میں داخل ہوا پھر جب سرمایہ دار نے حصول زر کے لئے کم سے کم خرچ پر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا چاہا۔تو اس طرح یورپ میں ایک غیر عادلانہ معاشی نظام وجود میں آگیا مزدور بے بسی اور محکومی کی زندگی بسر کرنے لگے۔سرمایہ دار ممالک میں بے روزگاری حیرت انگیز سرعت کے ساتھ بڑھنے لگی جب اس نظام کی مضرت، منفعت سے بڑھ گئی تو ان حالات میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں تو اس نظام سے اشتراکیت نے جنم لیا اس ضِمن میں آدم سمتھ اور ریکارڈو جیسے مفکرین نے اس نظام کے خلاف فکر تو دی ہوئی تھی مگر وہ اپنی فکر کو منظم نہ کر سکے تھے وہ صرف ایک نظریئے کی حد تک تھی۔پھر جب کارل مارکس نے اس نظام کے خلاف آواز بلند کی تو یہ آواز نظریئے کی حد سے نکل کرتنظیم کی شکل اختیار کر گئی تو کئی ممالک سے سرمایہ دارانہ نظام کا جنازہ نکل گیا اشتراکی فکر کی پہلی تجربہ گاہ روس تھا اس کے بعد یہ فکر عملی اور تنظیمی رنگ میں کئی دوسرے ممالک میں جاچکا ہے۔[vi]
اشتراکی خصوصیات
اب اس نظام کی چیدہ چیدہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔
1: نجی ملکیت کا خاتمہ :
اس نظام میں تمام ذرائع پیدائش دولت حکومت کی تحویل میں چلے جاتے ہیں جس سے نجی ملکیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ منافع جو تاجروں، زمینداروں اور کارخانہ داروں کی جیب میں جاتا تھا وہ حکومت کے خزانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح ریاست مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔
2: استحصال کا خاتمہ :
اجتماعی ملکیت سے استحصال کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس نظام کے تحت ذاتی منافع کے حصول کا امکان نہیں ہوتا اس وجہ سے کسی شعبے میں بھی زیر دستوں کا استحصال بند ہو جاتا ہے۔
3: طبقاتی کشمکش کا خاتمہ :
جب تمام پیدائش دولت کے ذرائع ریاست کے قبضے میں آجاتے ہیں آجروں کا وجود ختم ہو جاتا ہے جو طبقاتی کشمکش کا سبب ہوتا ہے ریاست میں صرف ایک طبقہ رہ جاتا ہے وہ کارندوں کا اور اشتراکی اصول کے مطابق وہی صاحب اقتدار ہوتے ہیں۔
4: جامع منصوبہ بندی :
حکومت ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت ذرائع پیدائش دولت کو زیادہ سے زیادہ مفید طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے ملک کی ضروریات باآسانی پوری کی جا سکتی ہیں۔
5: ضیاع وسائل کا خاتمہ :
چونکہ تمام وسائل پیداوار کا استعمال ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے اس لئے اشیاء ضرورت اتنی ہی مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے جس سے وسائل کا ضیاع ختم ہو جاتا ہے۔
6: ضروریات زندگی کی فراہمی :
پیدائش دولت کے وسائل ریاست کے تحت آجانے سے عوام کو ضروریات زندگی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور عوام کو معاشی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔
7: بے جا تفاوت کا خاتمہ :
نجی ملکیت سے ایک طبقہ امیر تر اور دوسرا اس کا محتاج ہوتا ہے۔سرمایہ دارانہ نظام سے آمدنیوں میں بے جا تفاوت ہوتا ہے جبکہ اشتراکیت کا کہنا ہے کہ عمرانی زندگی کے مصائب و آلام صرف جماعتی امتیازات کی بنیاد پر ہیں اور اس کا ازالہ مزدوروں کی جماعت کا برسر اقتدار آکر عالمگیر یکسانیت و مساوات پیدا کرنا ہے۔
8: ارتکاز دولت کا خاتمہ :
ہر شخص کو ریاست اس کی ضرورت کے مطابق اشیاء ضرورت فراہم کرتی ہے کسی کے پاس دولت کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس طرح کسی کے پاس دولت کا ارتکاز بھی نہیں ہو پاتا۔
9: معاشی ناہمواری و بے روزگاری کا خاتمہ :
صرف ریاست ہی کے تمام دولت کے مالک ہونے سے معاشی ناہمواری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ عوام کو روزگار مہیا کرنا بھی ریاست کاکا م ہے تو بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔
10: سود اور معاشی بحران کا خاتمہ :
اس نظام کے تحت سود ختم ہو جاتا ہے اور چونکہ کساد بازاری کسی بھی ملک میں معاشی بحران کا باعث ہوتی ہے جو کہ زائد از ضرورت پیداوار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی اس نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو معاشی بحران کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔یعنی اشتراکیت ایک ایسا معاشی نظام ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو مذہب کا انکار شامل ہے کارل مارکس کہتا ہے کہ ”مذہب انسانی ذہن کی پیداوار ہے“۔اور اس لادینی نظام کے اصولوں کے تحت جس معاشرے کا قیام وجود میں آ تا ہے اس میں نجی ملکیت نہ ہونے کے باعث انسان کی انفرادی جدوجہد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے،ہر بات میں ریاست کے بااختیار ہونے سے جمہوری رویئے کی بجائے جبر و کراہ ہوتا ہے، آمریت کی ترویج ہوتی ہے، علم کی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ جب ملنا صرف ضرورت کے تحت ہے تو آگے بڑھنے یا مزید محنت کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے،آزاد معاشرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نظام میں عوام برسر اقتدار طبقہ کے اقتصادی غلام بن جاتے ہیں اور وہ اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ان خصوصیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اشتراکی نظام غیر فطری اور غیر طبعی ہے اسی لئے یہ نظام اپنی صحیح صورت میں کسی بھی ملک میں رائج نہیں ہو سکا جب اس نظام کو روس میں عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو اس کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی کرنا پڑی۔عوام کو ایک حد تک ذاتی ملکیت رکھنے کی اجازت دی گئی اور اجرتوں میں بھی امتیاز قائم رکھا۔
ان دونوں انتہاؤں اور غیر فطری نظاموں کے مقابلے میں اب اسلامی نظام معیشت کے متعلق بات کی جارہی ہے مزید یہ کہ اسلامی طرز زندگی کے بنیادی تخصص عدل اجتماعی کے تناظر میں اس نظام کا جائزہ لیا جائے گا اور اسلامی نظام معاشرت میں اس کی اطلاقی نوعیت کی کیفیت کوسمجھتے ہیں۔
اسلامی نظام معیشت :
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر بہت سی نعمتوں سے نوازا اور اس کے ساتھ ہی چندحدود کو بھی مقرر کر دیا تاکہ انسان ان حدود کو توڑ کر دوسروں کا استحصال نہ کرے ان حدود ”حلال و حرام“ کے ساتھ عمدہ اخلاق کی تعلیمات بھی عطا کیں اور ان قوائد و ضوابط کے اطلاق کے لئے اسلامی طرز حیات کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی دیا جس کا اطلاق اسلامی طرزِ حیات کے تمام شعبہ ہائے جات پہ ہونا لازم ہے کیونکہ یہی اطلاق اسلامی نظام معاشرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔اسلام کا فلسفہ اخلاقیات اس کے تمام احکامات و تعلیمات پر حاوی ہے اور جیسا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو تمام شعبوں کی طرح معاشی شعبہ میں بھی ایک جامع مالیاتی نظام دیا جو کہ عین فطری ہونے کی وجہ سے ممکن العمل ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ اس میں بنی نوع انسان کے تمام معاشی مسائل کا حل ہے۔
اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات: اس نظام کی چند بنیادی خصوصیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو کہ اسے دیگر تمام نظام معیشت سے ممتاز کرتی ہیں۔
1: اللہ تعالیٰ ہی واحد رازق:
اسلام کے معاشی نظام کے تمام اصول و ضوابط طے شدہ ہیں جو کہ سراسر انسانیت کی فلاح کے لئے ہیں اور اس ضِمن میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائناتوں کے ہر طرح کے جانداروں کے رازق ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے :{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }[vii] "اور کوئی (رزق کھانے والا)جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہرایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے سب چیزیں کتاب مبین (یعنی لوح محفوظ) میں (منضبط اور مندرج ہیں۔"
مولانا عبد الرحمن کیلانیؒ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں : اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کے بھی رازق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جاندار کو اس کے مقام پر رزق پہنچائیں۔اس آیت سے جہاں اللہ تعالیٰ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے وہاں ان کے وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے ان کے رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتے ہیں جس سے زمین میں سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہیں پھر اسی نباتات، فصلوں اور پھلوں وغیرہ سے ہر جاندار کو بالواسطہ یا بلاواسطہ روزی مہیا ہوتی ہے اور ہر جاندار کی جملہ ضروریات زندگی اسی زمین سے مہیا ہو رہی ہیں۔اللہ تعالیٰ جس قدر مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اسی قدر زمین بھی خزانے اگلتی جا رہی ہے اور آئندہ بھی اگلتی جائے گی۔لیکن اس رزق کے حصول کے لئے انھوں نے اسباب و وسائل اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور جب کوئی انسان یا جاندار اسباب اختیار کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔یہاں ایک ضِمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رازق اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر ہزاروں لوگ قحط سے یا دوسری وجوہ سے کیوں مر جاتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ قحط تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے مسلط ہوتا ہے اور دوسری وجوہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی اور معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں۔یہ سب انسانوں کے کسبِ اعمال کا ہی نتیجہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔[viii]
قرآن حکیم متعدد بار اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ سب کے رازق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں تمام جانداروں
کو رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور سب کو روزی ان کی جائے پناہ میں دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے ان کے علم کا یہ حال ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بِل انہیں معلوم ہے اور اسی جگہ انہیں سامان زیست پہنچایا جا رہا ہے۔کچھ ارشاد ربانی ہیں:{وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}[ix] ”آسمان میں ہی ہے تمھارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے“
{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ }[x]”اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہیں، بڑی قوت والے اور زبردست“
عدل اجتماعی جو کہ اسلامی طرزِ حیات کا بنیادی تخصص ہے وہ ”اجتماعی کفالت باہمی“ کا اصول دیتا ہے جس میں بنیادی طور پر پہلی بات یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے ہر جاندار کے رازق صرف اللہ تعالیٰ ہیں یعنی معیشت اور اسباب معیشت خدائے تعالیٰ کے خزانہ عامرہ کی ایسی عطا اور بخشش ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھانے کا ہر شخص کو برابری کی سطح پر مساویانہ حق ہے۔یہ ایسا اصول ہے جو کہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا آج یہ جو عالمی سطح پر ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائل رزق اس کا ساتھ نہیں دے رہے لِہٰذا خاندانی منصوبہ بندی اور اولاد پر کنٹرول بہت ضروری ہے اس سلسلہ میں آج کے ماہر معاشیات کی کوتاہ فہمی اور فطرت سے جنگ کے نتیجہ میں ان کی ناکامی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں ایسے محکمے قائم کیے جا رہے ہیں شرح پیدائش نسبتاََ بڑھتی جا رہی ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ لوگ بھی پہلے سے زیادہ آسودہ اور خوشحال ہیں جس کا اندازہ ہر شخص اپنی پچاس سال پہلے کی زندگی سے کر سکتا ہے ان مادہ پرست ماہرین کے فکر کی اصل وجہ محض اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر عدم توکل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو آبادی کی افزائش کے ساتھ ساتھ زمین کے خزانوں میں اضافہ فرما رہا ہے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ رب کائنات پر توکل رکھا جائے۔
2: معاشی عدل :
اسلامی اقتصادی نظام کا بنیادی مقصد معاشرے میں معاشی عدل کے قیام کو یقینی بناناہے۔اس نظام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں معاشی سرگرمیاں مذہب و اخلاق سے جدا نہیں بلکہ معاش دین کا حصہ ہے اسی لئے قرآن کریم مال کو ”خیر“ اور معاش کو ”اللہ تعالیٰ کے فضل“ سے تعبیر کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے :{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }[xi]
”پھر جب نماز(جمعہ)پوری ہو چکے تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ)تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو اور (اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو“
پھر ایک جگہ مسلمانوں کے کردار پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ انھیں خرید و فروخت اور کاروبار زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہرگز غافل نہیں کرتے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔اس طرح سے ان کی ایسی نفسیاتی تربیت کر دی گئی کہ ہر معاملہ زندگی میں ان کی ترجیح صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو گی۔ارشاد ربانی ہے :{رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ }[xii]"جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت (اور) ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔"
اسلام اس نفسیاتی تربیت کے بعد اس بات کو واضح کرتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو اس بات کا مساویانہ حق حاصل ہے کہ وہ معیشت کے میدان میں جس قسم کی بھی چاہیں آزادانہ سرگرمیاں اختیار کر سکتے ہیں تمام پیدائش پیداوار اور وسائل پر سب کا بلا تفریق حق مسّلم ہے۔لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک فرد کے پاس برابر برابر دولت ہو اس قسم کا طرزِ فکر حیات اجتماعی کے برخلاف ہے کیونکہ اجتماعی نظام اسی وقت چلے گا جب معاشرہ میں مزدور بھی ہوں، مالک بھی ہوں، کم آمدنی کے لوگ بھی ہوں اور زیادہ آمدنی والے لوگ بھی ہوں۔یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہر شخص مختلف استعدادیں لے کر پیدا ہوتا ہے انہی استعدادوں اور قابلیتوں کی بنا پر وہ ترقی کرتا ہے ارشاد اِلٰہی ہے :
{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }[xiii]
”کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت (خاصہ یعنی نبوت) کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں دنیوی زندگی میں (تو) ان کو روزی ہم (ہی) نے تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک دوسرے رفعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور (عالم کا انتظام قائم رہے) اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہا اس (دنیوی مال و متاع) سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں“۔
یعنی اسلام میں معاشی عدل کا یہ مطلب ہے کہ تمام افراد کو ذرائع پیداوار میں حق انقفاع برابر سب کو حاصل ہو۔جاگیرداری نظام سے معاشرہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حق انقفاع سے محروم ہو جاتا ہے جو اسلام کے معاشی عدل کےسراسر منافی ہے لِہٰذا جاگیرداری نظام ناجائز اور باطل ہے۔
3: انفرادی ملکیت کا تصور :
اسلام کے تصور ملکیت کی رو سے تمام کائنات کے خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں لیکن معاملات زندگی کے لئے انسان کو محدود انفرادی ملکیت کا حق و تصرف دیا گیا ہے۔یعنی اسلام انفرادی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے لیکن شرائط اور قیود کے ساتھ کیونکہ ان شرائط اور قیود کے فقدان سے معاشی نظا م میں فساد کی راہ کھلتی ہے۔اسلام ایک فطری اور ابدی دین ہے جو زمان اور مکان کی قیود سے بالاتر ہے اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق اصولی تعلیم موجود ہے۔ زمانہ کے حالات اور تقاضوں کے مطابق زندگی کے مسائل کو اصولی تعلیم کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے اسلام نے انفرادی ملکیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی اس نے زمین کا ایک خاص مقصد بیان کیا ہے اس مقصد کے تحت انفرادی ملکیت کی زمانہ اور حالات کے پیش نظر حد بندی کی جا سکتی ہے۔[xiv] قرآن حکیم میں ارشاد ہے :{وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ }[xv]"اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو (اس کی جگہ) رکھ دیا۔"
مولانا عبد الرحمن کیلانی ؒ ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں : اناج سے مراد ہر وہ جاندار مخلوق ہے جو روئے زمین پر پائی جاتی ہے۔خواہ وہ چرند ہوں یا پرند،مویشی ہوں یا درندے،انسان ہوں یا جن ہوں مطلب یہ کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق ہم نے زمین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔یہی ان کی جائے پیدائش، ان کا مسکن اور ان کا مدفن ہے۔اس آیت سے اشتراکیت پسند افراد نے اپنا نظریہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمین حکومت کو اپنی تحویل میں لے لینی چاہیئے اس نظریئے کے ابطال کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انام کے معنی صرف انسان ہی نہیں بلکہ سب جاندار مخلوق ہے پھر اس پر کئی اعتراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں مثلاًیہ کہ کیا زمین کی تمام پیداوار تقسیم ہو گی یا مصنوعات؟ اور کیا ہر فرد ریاست میں برابر تقسیم ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اور آج تو ان لوگوں کا نظریہ عملاََ بھی باطل ثابت ہو چکا ہے۔ [xvi]
ان آیات کریمہ میں زمین کا مقصد وحیدیہ بیان کیا ہے کہ وہ مخلوق کے لئے اناج، پھل، پھول وغیرہ پیدا کرے اس اصول کی روشنی میں زمانہ کے تقاضے کے مطابق زرعی نظام قائم کیا جائے گا۔
4: کسب حلال :
اسلام کا معاشی نظام تمام انسانوں کو ایک متحرک اور بامعنی زندگی دیتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پہ توکل و یقین کے ساتھ ساتھ ذاتی جدو جہد کو بہت اہم مقام حاصل ہے جو کہ ایک کامیاب زندگی کے لئے بہت ضروری ہے۔اسلامی نظام حیات کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی ہرگز اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ انسان بالکل ہی اپنے رب پہ یقین نہ کرتے ہوئے صرف اپنی ذاتی قابلیت و صلاحیت پہ بھروسہ کرے اور اس جدوجہد میں کسی حدود و قیود کا خیال نہ کرے کیونکہ اس طرزِ عمل سے ایک غیر مستحکم اور خود غرض معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور نہ ہی انسان کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ صرف اپنے رب پہ توکل کر کے بیٹھا رہے اور خود کوئی کوشش و جدوجہد نہ کرے کیونکہ اس سے ایک کاہل اور ناکام معاشرہ وجود میں آئے گا۔یہ دونوں صورتیں ہی اسلام کو ناقابل قبول ہیں بلکہ اسلام تو ایک ایسے معاشرے کا داعی ہے جو کہ ایک متحرک اور مستحکم معاشرہ ہے جس میں عدل اجتماعی اپنی تمام تر صورتوں میں نافذ ہو اکیونکہ اسی فلسفہ میں انسانوں کی کامیابی و فلاح پوشیدہ ہے۔اور یہ معاشرہ صرف کتابی باتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ دور نبوی ﷺاور خلافت راشدہ میں اس معاشرے کی عملی شکل انسانی تاریخ کا سنہرا باب ہے حضور نبی کریم ﷺ نے کسب حلال کو فریضہ بعد الفریضہ قرار دیا یعنی عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض اسی کو قرار دیا ارشاد ربانی ہے:{وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ }[xvii]”اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمھارے لئے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو“۔
حافظ ابنِ کثیرؒ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا :اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرما رہے ہیں کہ انھوں نے زمین اپنے بندوں کے رہنے سہنے کے لئے بنائی اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ زمین ہلے نہیں اس میں چشمے جاری کئے اس میں منزلیں اور گھر بنانے کی طاقت انسان کو عطا فرمائی اور بہت سی نفع کی چیزیں اس کے لئے پیدا فرمائیں ابر مقرر کر کے اس میں سے پانی برساکر ان کے لئے کھیت اور باغات پیدا کئے۔تلاش معاش کے وسائل مہیا فرمائے۔تجارت اور کمائی کے طریقے سکھا دیئے۔باوجود اس کے بہت سے لوگ پوری طرح شکر گزاری نہیں کرتے۔ [xviii]
یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لئے کائنات میں رزق کے وسائل مہیا کر رکھے ہیں اور بنی نوع انسان کے لئے ہر طرح کے پیدائش وسائل مہیا کئے۔اب ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے رزق کی تلاش میں سعی و جدوجہد کرے اور اپنے رب کا شکر گزار بنے جس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا۔کسب حلال کے ضِمن میں اسلام نے ایک مکمل تصور دیا کہ جس کے تحت حلال،حرام و جائز، ناجائز اور صحیح و غلط کی نہ صرف تمیز دی بلکہ باقائدہ حدود و قیود کے تحت اصول وضع کئے اس بات کو دو پیراؤں میں دیکھا جا سکتا ہے مثلاً:
1: اکل حلال :
اس سے مراد دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان صر ف جائز اور حلال طریقوں سے اپنا معاش حاصل کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جائز طریقوں سے معاش حاصل کر لینے کے بعد اس سے حلال اور طیب اشیاء کھائے اور ان کے علاوہ بھی جتنے مصارف ہیں وہ سب جائز ہونے چاہئیں ارشاد باری تعالیٰ ہے :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }[xix]"لوگو!زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پہ مت چلو وہ تمھارا کھلا دشمن ہے"
مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت مبارکہ کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے حلال یہ ہے کہ اس کے اصل وجوہ میں کوئی ایسی خرابی و قباحت نہ پائی جاتی ہو،جس کی بنا پر شریعت مطہرہ نے اس کو حرام و ممنوع قرار دیا ہو ایسی حرام و ممنوع چیزوں کا اخذ و تناول جائز نہیں ہو گا جیسے خمر، خنزیر، میتہ اور دم مسفوح وغیرہ۔اور طیب و پاکیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے حصول و اکتساب میں کسی حرام وممنوع فعل کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو جیسے چوری، ڈکیتی، غصب، دھوکہ اور سود و قمار وغیرہ سے حاصل کردہ مال۔پس جو اشیاء حلال و طیب ہو ں کہ ان کے اصل وجود میں بھی کوئی خرابی نہ ہو اور ان کے حصول میں بھی کسی فعل ممنوع اور برائی کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو،ان سے استفادہ کرو۔انھیں کھاؤ، برتو اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر بجالاؤ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی عمدہ اور پاکیزہ تعلیمات دی ہیں اور ایک ایسا دین عطا کیا کہ جس کی تمام تعلیمات عقل و فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہیں اور بنی نوع انسان کی سعادت و سرخروئی کی کفیل و ضامن ہیں۔مگر انسان کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ ان سنہری تعلیمات کو چھوڑ کر ظلمت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے انجام و نتیجہ سے قطعی لاعلم اور بے پرواہ ہے۔ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ:”بہترین عمل روزی کمانا ہے“۔”حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی“۔
2: ناجائز ذرائع آمدن اور مصارف :
اسلام ایک دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے اس کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر نافذ ہونا ضروری ہے۔اکل حلال کے احکامات کے بعد اسلام ان ذرائع آمدن کی ممانعت بھی فرماتا ہے جو کہ ناجائز ہیں اور اس کے ساتھ ان تمام مصارف کا بھی کہ جن پر خرچ کرنا ناجائز ہے مثلاً:
1: حرمت سود :
اسلام تو امن و سلامتی اور اخوت و بھائی چارہ کا دین ہے جو کہ احترام انسانیت اور باہمی تعاون کا درس دیتا ہے لِہٰذا یہ ہر اس کام سے منع کرتا ہے کہ جس سے کسی کا بھی استحصال ہوتا ہو اس لئے ایسے تمام ذرائع آمدن کو ناجائز قرار دیا جو کہ کسی دوسرے انسان کے لئے نقصان دہ ہوں۔سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے لوگوں کا بہت سنگین طریقے سے معاشی استحصال ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }[xx]
”اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمھارا اصل مال تمھارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے“ ۔
عدل اجتماعی تو انسان کی نفسیاتی تربیت ان خطوط پہ کرتا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں یہ آپس میں محبت، ہمدردی، مروت اور ایک دوسرے پر رحم و ایثار کا سبق سکھاتا ہے نبی کریمﷺ نے ساری زندگی صحانہ کرام ؓ عنہم کو اخوت و ہمدردی کا سبق دیا۔جبکہ سود انسان میں ان سے بالکل متضاد رذیلہ صفات مثلاً بخل، حرص، زرپرستی اور شقاوت پیدا کرتا ہے اور بھائی بھائی میں منافرت پیدا کرتا ہے جو کہ عدل اجتماعی کی عین ضد ہے۔دوسرا یہ کہ اسلامی معاشی نظام کا تمام تر ماحصل یہ ہے کہ دولت گردش میں رہے اور اس گردش کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف رہے اسی لئے نظام زکوٰۃ و صدقات کو فرض کیا گیا اور قانون میراث اور حقوق باہمی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔جبکہ سودی معاشرہ میں دولت کا بہاؤ ہمیشہ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی عین ضد ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ”لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہو گا اور اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار (اور ایک دوسری روایت کے مطابق) اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کے رہے گا“۔
آج کا دور وہی ہے پوری دنیا کے لوگوں اور اسی طرح مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں بھی سود اس طرح سرایت کر چکا ہے جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پہ متاثر ہو رہا ہے۔یہ سب اس سودی استحصالی نظام کی وجہ سے ہے جس کے چنگل میں ساری دنیا جکڑی ہوئی ہے اور ترقی یافتہ بڑی طاقتوں نے ترقی پذیر ممالک کو سودی قرضوں میں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس نظام سے نکل نہیں پا تے۔ نبی کریمﷺ نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا معاہدہ لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان سب کو سود کے گناہ میں برابر شمار کیا ہے آپ ﷺ نے سود سے بچنے کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ قرض خواہ کو قرضدار سے ہدیہ تک لینے سے بھی منع فرما دیا۔
2: احتکار کی روک تھام :
سرمایہ دار سود کو بڑھانے کے لئے سرمایہ کا بڑا حصہ روک لیتا ہے جس وجہ سے ضرورت مند مجبور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ شرح سود سے قرض لے کر اپنا کاروبار چلائے بعض اوقات کاروبار میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ تاجر اپنے کاروبار کو خسارے سے بچانے کے لئے شرح سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے سرمایہ دار اس قسم کے مواقع کی تاک میں ہوتا ہے ایسے میں وہ اپنا سرمایہ روک لیتا ہے پھر ضرورت مند کو زیادہ شرح سود پہ قرض دیتا ہے اس طرح صنعت کار زیادہ شرح سود پہ قرض لینے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرے گاجس کا اثر اور بوجھ عوام پہ پڑے گا۔ اس سے عوام کی معاشی حالت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی تجارت و صنعت کو بھی نقصان پہنچتا ہے تبھی اسلام نے سود سے منع کرنے کے ساتھ احتکار کرنے والے کو بھی عذاب عظیم کی خبر دی ہے۔
3: اکتناز کی ممانعت :
علم معاشیات کا سادہ سا اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں غربت اور بے روزگاری ا س وقت پیدا ہوتی ہے جب امراء میں دولت جمع کرنے کا رجحان عام ہوجاتا ہے اسی لئے اسلام نے اکتناز سے منع فرمایا ہے ارشاد اِلٰہی ہے: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ }[xxi]"اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انھیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انھیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔"
حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :ضرورت سے زائد جمع کرنے کو کنز کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے جہاں اسلام اکتساب دولت کی ترغیب دیتا ہے ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ کمائی ہوئی دولت صرف تمھاری ملکیت نہیں ہے اس میں سائلین اور محرومین کا بھی حق ہے۔معاشرتی و اقتصادی تفریق کو کم کرنے کے لئے بھی یہ حکم دیتا ہے کہ زائد از ضرورت مال اللہ تعالیٰ کی راہ (اسلامی ریاست) میں خرچ کر دے۔یہ ایک ایسا پائیدار اصول ہے جو کہ خود بخود معاشرے میں سے اقتصادی تفاوت کو ختم کرتا ہے کیونکہ معاشی تفاوت اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب صاحب ثروت لوگ اپنی کمائی ہوئی دولت کو صرف اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ پیسہ اپنے علم، ہنر اور قابلیت کی بنا پر حاصل کیا ہے اس وجہ سے وہی مالک ہے چاہے تو کسی کو دے نہ چاہے تو نہ دے۔[xxii] حضور بنی کریم ﷺ نے فرمایا : ((عن زید بن أسلم، أن أبا صالح ذکوان، أخبرہ أنہ سمع أبا ھریرۃ،یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من صاحب ذہب ولا فضۃ، لا یؤدی منہا حقہا، إلا إذا کان یوم القیامۃ، صفحت لہ صفائح من نار، فأحمی علیہا فی نار جہنم، فیکوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، کلما بردت أعیدت لہ، فی یوم کان مقدارہ خمسین ألف سنۃ، حتی یقضی بین العباد، فیری سبیلہ، إما إلی الجنۃ، وإما إلی النار( )[xxiii]
4: اسراف و تبذیر کی ممانعت :
اسلام کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی نہ صرف ذرائع آمدن کے متعلق حدود و قیود کا تعین کرتا ہے بلکہ اس کے بعد اس کمائی ہوئی دولت کے اصراف کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے کہ اپنی کمائی کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے جائز طریقے سے خرچ کرے۔اور مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کی گئی اور اس ضِمن میں میانہ روی کو معیار بنایا گیا یعنی نہ تو بالکل ہی فضول خرچی کرے اور نہ ہی کنجوسی اختیار کر لے۔اسلام نے حق استعمال و تصرف پر چند حدود و قیود عائد کی ہیں اس کو احادیث میں حجر کہا گیا ہے جس کے لفظی معنی ”ممنوع“ کے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۔إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}[xxiv]
”اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اصراف اور بے جا خرچ سے بچو۔بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔“
سید قطب شہیدؒ ان آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں : ان آیات مبارکہ میں اصراف اور تبذیر سے روکا گیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اصراف سے مراد ضروری کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں مثلاً اپنے کھانے پینے میں اور لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا اصراف ہے۔جبکہ تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے فخر، ریا، نمود و نمائش اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے۔اسی لئے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا کیونکہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔تو جن لوگوں کا یہ طرزِ عمل ہو انھوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت مال کو غلط راستوں میں خرچ کر کے اپنے رب کی ناشکری کی۔ [xxv]
اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں پہ چار پنکھے چل رہے ہوں جبکہ کام دو پنکھوں سے بھی چل سکتا ہو تو یہ اسراف ہے۔اور اگر وہ لوگ باہر جانے سے پہلے ان پنکھوں کو چلتا چھوڑ جائیں تو یہ تبذیر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا :{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}[xxvi]”اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے ہی باندھ لینا چاہیئے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیئے ورنہ الزام خوردہ تہی دست ہو کے بیٹھ رہو گے“۔
نبی کریم ﷺ کا اسوۂ حسنہ اس سلسلے میں بہترین مثال ہے آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:
(( اخبرنا احمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كلوا وتصدقوا، والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة))[xxvii]
"عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کھاؤ، صدقہ کرو، اور پہنو، لیکن اسراف (فضول خرچی) اور غرور (گھمنڈ و تکبر) سے بچو۔"
5: انفاق فی سبیل اللہ :
اسلام کے معاشی نظام میں خرچ کرنے کے باقائدہ ذرائع دیئے گئے کہ جن کے ذریعے خرچ کیا جائے۔سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ اقتصادی نظریئے کی بنیاد طیب اور حلال رزق پر ہے اور اپنی ذات و اہل وعیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ اور طریقوں سے بھی خرچ کرنے کی تلقین کی گئی اور مال کو محض ذاتی فائدے کے لئے جوڑ کر رکھنے کی ممانعت کی گئی ارشاد ربانی ہے :{وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۔۔۔الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ}[xxviii] ”بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور طعنہ دینے والا ہو۔جو (غایت و حرص سے) مال جمع کرتا ہو اور (غایت حسب فرح سے) اس کو بار بار گنتا ہو"
اسلامی اقتصادی نظام ایسے اصول وضع کرتا ہے کہ جس سے معاشرہ میں دولت گردش کرتی رہتی ہے اور یہ مرتکز نہیں ہو پاتی جس سے چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہ جاتی جیسا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے۔یہ اسراف و تبذیر اور ناجائز ذرائع پر خرچ کرنے سے روکنے کے بعد بتاتا ہے کہ اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پورا کر لینے کے بعد وہ اپنا مال خرچ کرے انفاق کی دو اقسام ہیں ایک تو لازمی زکوٰۃ اور دوسری طوعی خیرات ہیں مثلاً زکوٰۃ کو دین کا بنیادی رکن قرار دے کر فرض قرار دیا۔پھر انفاق فی سبیل اللہ میں صدقات واجبہ فطرانہ وغیرہ شامل ہیں قانون وراثت دیا گیا۔علاوہ ازیں حق سوی الزکوٰۃ (ضرائب یا زائد ٹیکسوں کا نفاذ)، عفو کا نظریہ بھی اسی ضِمن کی کڑیاں ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ }[xxix]”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ“
اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت پہ اور بھی بہت جگہ حکم آیا یہ دین کا تیسرا اہم رکن ہے۔حضور نبی کریم ﷺ نے اس پر انتہائی زور دیا اور بعد میں جب کچھ لوگ منکر زکوٰۃ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جس سے اس کی اہمیت مزید عیاں ہوتی ہے۔
{مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ }[xxx]
”کون ہے جو اللہ کو (نیت) نیک (اور خلوص سے) قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لئے عزت کا صلہ (یعنی جنت) ہے۔“
قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فقراء، اقربا اور مساکین کو دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے میں تو انفاق کی تمام صورتیں آجاتی ہیں۔{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}[xxxi]
"وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کونسا مال خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔"
یعنی ضرورت سے زائد سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا انفاق ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر بعد میں تہی داماں رہ جائے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے :۔ (ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ)”ان کے اموال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہیں“۔
عدل اجتماعی کی اطلاقی نوعیتیں :
عدل اجتماعی کے تناظر میں اسلامی نظام معیشت کی بنیادی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب اس کی کچھ اطلاقی نوعیتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جن کی روشنی میں معلوم ہو گا کہ معاشرے میں اس پر عمل پیرا ہونا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اور نتیجتاً معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔عدل اجتماعی کے تناظر میں ان اقدار کا احاطہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔
1: تقویٰ :
تقویٰ وہ پہلی قدر ہے جس پر اسلامی نظام اقتصاد کی بنیاد ہے قرآن حکیم میں جس اخلاقی قدر کا زیادہ اورمختلف پیراؤں میں ذکر ہوا ہے وہ تقویٰ ہے اور اسلام نے نظری اور عملی تعلیمات کی روح تقویٰ کو قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ }[xxxii] ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اوّل) اس سے اس کا جوڑا بنایا“۔
اس آیت نے تقویٰ کی وضاحت کر دی کہ تقویٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت ہے حقوق العباد میں
سب سے اہم حق ان کی جسمانی ربوبیت ہے جب قرآنی لفظ تقویٰ کے معنی معاشی امور کو سامنے رکھ کر طے کریں گے تو معنی ہوں گے جو کہ قرآن مجید ہی طے کرتا ہے :
{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }[xxxiii]”اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محرومین کا حق ہے“
یعنی متقی وہ شخص ہے جو کہ اپنے اموال میں سائلین اور محرومین کو حقدار سمجھے۔ عدل اجتماعی جس طرز پہ انسان کی نفسیاتی تربیت کرتا ہے ان اقدار میں یہ اہم قدر ہے۔
2: احترا م انسانیت :
اسلام کے نزدیک ہر انسان محض انسان ہونے کی حیثیت میں تحریم و تکریم کا مستحق ہے ارشاد ربانی ہے: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ }[xxxiv] ”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی“۔
عدل اجتماعی جب عدل کی بنیاد پر انسانی مساوات کے اصول کے تحت انسانیت کی تکریم کی بات کرتا ہے تو عملی بنیادوں پر اس کی تکریم کے لئے ضروری ہے کہ ہر فرد کی بلا تفریق تمام معاشی ضروریات کو پورا کیا جائے اور اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے نہ پڑیں کیونکہ ایسا کرنا انسانیت کی تکریم کے منافی ہے یہ طرزِ فکر اقتصادی نظام میں دوسروں کی مالی اعانت کے لئے ایک بہت بڑی ترغیب و تحریک ہے۔
3: اخوت :
اخوت توحید کا لازمہ ہے انسانی مساوات کا وہ زریں اصول وضع کرتا ہے جو اتنا کامل اور جامع ہے کہ معاشرے میں اس کا مثبت اطلاق معاشی مسائل کے حل پر منتج ہو گا۔حضور نبی کریم ﷺ نے مہاجرین کا مسئلہ اخوت کے اصول کے تحت ہی حل کیا تھا اور ایک روشن مثال قائم کر دی۔ اور اس اصول اخوت میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ معاشرے کے تمام افراد شامل ہیں۔ارشاد ربانی ہے :{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }[xxxv]"جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں اُن کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اُن کو (قیامت کے دن)نہ کسی طرح کا خوف ہو گا اور نہ غم"۔
حضرت ابو ہریرۃ ؓ سے بخاری و مسلم میں ایک طویل حدیث قدسی مروی ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں تیرے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا اور پہننے کو کپڑے نہ تھے مگر تم نے میری مدد نہیں کی تھی توبندہ کہے گا کہ اے میرے رب آپ تو مالک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ فلاں وقت میرا ایک مجبور بندہ اس حالت میں تیرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔
لوگوں میں اخوت، بھائی چارہ پیدا کرنے کے لئے یہ ترغیب کا بہترین انداز ہے۔جس معاشرہ کی بنیاد عدل اجتماعی کے تناظر میں اخوت پر ہوگی اس میں ہر فرد اپنی دولت کو مفاد عامہ کے لئے وقف کر دے گا یہی وہ اسلامی نظام معاشرت ہے جس میں ہر فرد دوسروں کی ربوبیت کی فکر میں رہتا ہے ان کے مفاد کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے "{وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }[xxxvi]
”اور اپنے دل میں ان کے لئے تنگی نہیں پاتے اس چیز سے جو ان کو دے دی جائے اور ان کو اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ اپنے اوپر فاقہ ہو اور جو اپنے اندر کے لالچ سے بچ جائے اس کے لئے فلاح ہے“
4: مساوات :
عدل اجتماعی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو انسانیت کے مقام پر برابر قرار دیتا ہے ان میں کوئی نسلی، لونی اور لسانی امتیاز نہیں کرتا۔ارشاد ربانی ہے: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ }[xxxvii]
”اور بے شک ہم نے تم کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمھارے لئے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو“
یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو سامان معیشت کے خزانے پیدا کئے وہ سب انسانوں کے فائدے کے لئے یکساں ہیں کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا صرف کوشش اور جدوجہد لازم ہے اور معاشرے میں جو معاشی تفاوت نظر آتی ہے وہ انسانوں کی صلاحیتوں اور فطرت کے مطابق ہے نیز ان کی سعی و جدوجہد کے مطابق ہے مزید یہ کہ صاحب ثروت کو مصالح عامہ کے لئے خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
5: عدل :
عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اوراللہ تعالیٰ کا تمام نظام کائنات عدل کی بنیاد پر ہی قائم و دائم ہے جس کی وجہ سے ہی کائنات کا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے اور یہی ہدایت انسانوں کے لئے بھی ہے کہ وہ اس اصول کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔عدل اجتماعی جب اقتصاد کو عدل کے دائرے میں لاتا ہے تو اس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ پیدائش دولت، صَرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت میں توازن اور تناسب کو قائم رکھا جائے تاکہ نظام معاشیات صحت مند خطوط پر گامزن رہے اور تمام افراد معاشرہ اپنی احتیا جات زیست کو پورا کر سکیں۔
پیدائش دولت اور عدل :
پیدائش دولت میں عدل ہی وہ قدر ہے جو کہ سب کو حلال رزق کمانے کے اصول بتاتی ہے اور اکتساب حرام
کے تمام زرائع سے روکتی ہے ارشاد ربانی ہے :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ }[xxxviii]
”اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے (شرعی) حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ چلو کیونکہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے“
اسلام پیدائش دولت میں حلت کا ذکر کرنے ے ساتھ ساتھ حرام طریقوں کا بھی بالصراحت ذکر کر دیتا ہے یعنی سود، احتکا ر، اکتناز، رشوت، کاروبار میں بددیانتی اور بیوع میں دھوکہ دہی وغیرہ شامل ہیں کیونکہ ان ناجائز طریقوں سے عدل کے ترازو کا پلڑا ناجائز کمائی کرنے والوں کی طرف جھُک جاتا ہے جو کہ معاشرے میں معاشی عدم توازن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اسی لئے ان کی ممانعت کر دی گئی۔ [xxxix]
٭ صَرف دولت اور عدل :
پیدائش دولت کے بعد صَرف کی باری آتی ہے یعنی کمائی ہوئی دولت کو کیسے خرچ کیا جائے اسلام اس ضِمن میں عادلانہ اصول دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}[xl] ”اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا“۔
اس کے علاوہ وہ تمام احکامات جن کا ذکر کیا جا چکا ہے عدل اجتماعی انسان کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ انسان ان اصولوں پر عمل پیرا رہتا ہے جو کہ ایک مستحکم معاشرے کے لئے بنیادی اینٹ کی سی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ جب انسان عدل اجتماعی کے اخلاقی فلسفہ پر گامزن رہے گا تو ان سب احکامات پہ عمل پیرا ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔
٭ تقسیم دولت اور عدل :
دنیا کے جتنے بھی معاشی نظام ہیں ان سب میں ایک بڑی خرابی تقسیم دولت کی ہے کیونکہ وہاں عدل کو قائم نہیں رکھا گیا اسی لئے ان نظامو ں میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے اسلام تقسیم دولت کے لئے انفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے ارشاد ربانی ہے :{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }[xli]"جو غیب پرایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔"
یعنی انفاق کی وہ تمام صورتیں اس میں شامل ہیں جو کہ پہلے بیان کی جا چکی ہیں اور وہ تمام ناجائز ذرائع جن کی ممانعت قرار دی گئی۔اب ان دونوں صورتوں کے لئے انسان کو ترغیب و تحریک عدل اجتماعی کا وہ اخلاقی فلسفہ دیتا ہے جو کہ اس کا خاصہ ہے جو کہ ایک مومن کو ذات باری تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلاتا ہے اور دنیاوی و اخروی فلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔
٭ تبادلہ دولت اور عدل :
اسلام کے اقتصادی نظام کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ اشیاء کا تبادلہ باہمی رضامندی سے ہو اور کسی قسم کا کوئی جبر و کراہ نہ ہو۔ارشاد ربانی ہے :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ }[xlii]
”مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے “
آپؐ نے فرمایا : (لا ضرر و لا ضرار)"نہ تو ضرر لیا جائے اور نہ ہی ضرر دینا جائز ہے"۔یعنی تبادلہ لین دین میں ہو قسم کے باطل طریقوں سے منع کر دیا گیا جن میں بیع ملامسہ، بیع الحصاۃ، بیع منابنہ، بیع محاقلہ وغیرہ شامل ہیں۔
6: احسان :
قرآن حکیم عدل کے بعد احسان کا حکم دیتا ہے ارشاد ہے :{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}[xliii] ”بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتے ہیں“
عدل اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا نام ہے جس میں کسی کا بھی حق دینے میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیئے خواہ مالی ہو خواہ تعزیری حق ہو اس کو کماحقہ ادا کرنے کا نام عدل و احسان ہے۔ انسانی معاملات میں عدل ایک اعلیٰ ترین قدر ہے لیکن عدل کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہیں سے احسان کی حد شروع ہوتی ہے اور جب احسان کی حد اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو معاشرے میں غربت کافور ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں انفاق اور قوموں کی زندگی و ترقی کو لازم و ملزوم قرار دیا گیاہے۔ اور جب احسان شعبہ معیشت میں آ جائے تو وہ اسی زمرے میں آجاتا ہے کہ جس میں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا جاتا ہے جیسا کہ دور نبوی ﷺ اور عہد خلافت میں یہ طرزِ عمل اپنی بہترین شکل میں نظر آتا ہے اور اس کی بنیادی خاصیتوں میں انفاق اور عفو خصوصی طور پہ قابل ذکر ہیں۔ یہ اخلاقی اصول محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیا ر کئے جاتے ہیں اور صلے کی امید بھی صرف اپنے رب سے کی جاتی ہے کوئی دنیاوی فائدہ اس میں پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔
7: تعاون :
عدل اجتماعی کے اطلاق سے اسلامی نظام معاشرت میں ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو کہ باہمی تعاون پر مبنی ہوتی ہے اس معاشرتی زندگی میں افراد باہمی حقوق وفرائض کو تعاوب باہمی کے سائے میں ادا کرتے ہیں جس سے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں تب فرض صرف فرض نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بن جاتا ہے اور اس احساس سے معاشرتی زندگی نشوونما پاتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }[xliv]”نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو“
اب یہاں صرف تعاون کی تلقین نہیں کی گئی تعاون کی حدیں بھی مقرر کر دی گئیں کہ تعاون نیکی اور اچھائی کے کاموں میں کیا جائے جس سے معاشرتی زندگی پہ اچھا اور صحتمند اثر پڑے اور ایسا تعاون جس سے تمدنی زندگی میں فساد پیدا ہوتا ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور فساد پیدا کرنے والے دو اموراثم اور عدوان کا ذکر کر دیا گیا یعنی تمام ناجائز اور گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ عدل اجتماعی مبنی بر حقیقت فلسفہ ہے اور جانتا ہے کہ معاشی مسائل باہمی تعاون کے بغیر حل نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ ﷺ نے مومنین کی مثال ایک عمارت سے دی کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے جس کا عملی نمونہ مواخات مدینہ کے موقع پر نظر بھی آتا ہے۔
یہ ہے وہ اسلام کا معاشی نظام جو کہ اسے دیگر تمام معاشی نظاموں سے ممتاز کرتا ہے اور یہ خود اپنی ذات میں اس قدر جامع اور کامل نظام ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بھی نظام ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ یہ نظام خود رب کائنات اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے کسی انسان کا بنایا ہوا تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی یا جھول پایا جائے۔ انسان کو تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیئے کہ جس نے اس پہ احسان کرتے ہوئے اسے ایک نظام حیات سے نوازا مگر بدقسمتی سے انسان اس نظام حیات کوفراموش کئے ہوئے ہے اور گمراہی کے راستوں پہ بھٹک رہا ہے اس کی حقیقی فلاح و نجات کا واحد راستہ اسی نظام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔
خلاصہ:(Conclusion)
اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا معاشی نظام ایک مستحکم اور پُر رحمت معاشی نظام ہے جس کی بنیاد”انسان دوستی“ پر ہے۔جو بھی کچھ ہے انسان کے لئے ہے اور جو کچھ کیا جائے گا وہ انسانوں کی فلاح کے لئے ہی کیا جائے گا۔اسلامی نظام حیات کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی اسلامی اقتصادی نظام کے اتنے جامع اور ہمہ گیر تخصصات واضح کرتا ہے کہ جس سے اس نظام کی حقانیت اور بھی واضح ہوتی ہے۔یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لئے قابل عمل اور فلاح کی ضمانت ہے اور اس نظام کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد مساوات پر نہیں بلکہ معاشی عدل پر ہے۔اسلام اقتصاد کے باب میں جو پالیسی اختیار کرتا ہے عدل اجتماعی اس نظریئے اور طرزِفکر کے متعلق اپنا ایک تخصص رکھتا ہے اور لوگوں میں اس حقیقیت کا ادراک پیدا کرتا ہے کہ اس ضِمن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اصول قائم ہو جس کا طریقہ یہ ہے کہ دولت کا استعمال اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہو جائے، یہ قانون فرد اور جماعت دونوں کے مصالح کی پوری رعایت رکھتے ہوئے اس سلسلے میں ایک موزوں اور مناسب درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے جس میں نہ تو فرد کی حق تلفی ہوتی ہے،نہ جماعت کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، وہ نہ تو فطرت کی راہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہ زندگی کے انمول حقیقی ضوابط یا اس کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اس پالیسی کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانےکے لئے اسلام دو بنیادی طریقے اختیار کرتا ہے یعنی قانونی ضابطہ بندی اور ہدایت و تلقین۔قانون کے ذریعے وہ ایسے عملی مقاصد حاصل کرتا ہے جو اپنی جگہ ایک صالح اور ترقی پذیر معاشرہ کی تعمیر کے لئے کافی ہیں اور ہدایات و تلقین کے ذریعے وہ حاجات کی غلامی سے بلند ہونے اور زندگی کے بلند ترین مقاصد کی طرف متوجہ ہونے جیسے اعلیٰ مقاصد کی طرف اقدام کرتا ہے۔
مزید تحقیق کے لئے چند ممکنہ نکات:
اس موضوع کے متعلق مزید تحقیق کے لئے مندرجہ ذیل نکات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں:
1: عدل اجتماعی کی باقی اطلاقی نوعیتوں پر بحث کی جا سکتی ہے اس ضِمن میں معاشرے کے معاشی عنصر کے بعد باقی بنیادی عناصر کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے مثلاََ معاشرتی، قانونی و انتظامی ، عدالتی نوعیت پر عدل اجتماعی کی اطلاقی صورتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے ۔
2: عصری تناظر میں عدل اجتماعی کے ناپید ہونے کی بنا پر اطلاقی نوعیتوں کے عدم استحکام ، اضمحلال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں اس کے عدم وجود کے باعث کس طرح کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاًان اثرات میں معاشرتی انتشارو فساد، معاشی پسماندگی ،قانونی و انتظامی نقائص ،عدالتی نا کا میاں وغیرہ شامل ہیں ۔
3: منفی اثرات کو ختم کرنے کے لئے عدل اجتماعی کے تناظر میں اسلامی نظام معاشرت کے ان تخصصات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ جن کے عملی اطلاق کی صورت میں معاشرہ ترقی و فلاح کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے ۔
[i] غلام رسول چیمہ، پروفیسر، اسلام کا معاشی نظام نظام (چوہدری غلام رسول اینڈ سنز پبلشرز، لاہور،2012ء)ص:19
Ghulām Rasūl, Chīma, Professor, Islām kā Mu’āshi Nizām., Ch Ghulām Rasūl and Sons Publishers, Lahore ,2012, P:19
[ii] Comparative economic system p.112
[iii] www.economicshelp.org/blog/glassary/capitalism-v-socialism
[iv] www.econlib.org.library/enc/socialism.html
[v] لیاقت علی خان نیازی، ڈاکٹر، اسلام کا انتظامی قانون (دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، لاہور،2001ء)ص: 404،402
Liāquat Alī Khān, Niāzī, Dr., Islām kā Intezāmi Qānūn, Lahore, Dīyāl Singh Trust Library, 2001.P:402,404
[vi] www,idebate.org/debatabase
[vii] ہود 6:11
Sūrah hūd, 11:6
[viii] کیلانی، عبدالرحمٰن، مولانا، تیسیرالقرآن ( پاکستان، اسلامک پریس، لاہو ر، س۔ن) ص: 233
Kailāni, Ābdūl Rehmān, Mawlānā, Taīsīr-ūl-Qur’ān, Lahore, Pakistan, Islamic Press, S.N., P:233
[ix] الذاریات 22:55
Sūrah al-zārīyāt, 55:22
[x] الذاریات 58:55
Sūrah al-zārīyāt, 55:58
[xi] الجمعہ 10:62
Sūrah al-jumuah, 62:10
[xii] النور 37:24
Sūrah al-nūr, 24:37
[xiii] الزخرف 32:43
Sūrah al-zūkhrūf, 43:32
[xiv] اسلام کا معاشی نظام (چوہدری غلام رسول اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، 2012ء)ص:113
Islām kā Muāshi Nizām., Ch Ghulām Rasūl and Sons Publishers Lahore,2012, P:19
[xv] الرحمن 10:55
Sūrah al-rehmān, 55:10
[xvi] تیسیرالقرآن ،ص: 848
Taīsīr-ūl-Qur’ān, P:848
[xvii] الاعراف 10:7
Sūrah al-a’rāf, 10:7
[xviii] ابن کثیر، عماد الدین،تفسیر ابن کثیر (شمع بک ایجنسی، لاہور، 2004ء) ص: 148،147 ملخصاََ۔
Ibn-e- Kasīr, Imādudīn, Tafsīr Ibn e Kasīr, Lahore, Shamā Book Agency. 2004. P:147,148
[xix] البقرۃ 168:2
Sūrah al-baqarah, 2:168
[xx] البقرۃ 279:2
Sūrah al-baqarah, 2:279
[xxi] سورۃ التوبۃ 35:9
Sūrah al-taūba, 9:35
[xxii] تفسیر ابن کثیر (لاہور، شمع بک ایجنسی،1/2004،2ء) ص: 341،340ملخصاََ۔
Tafsīr Ibn e Kasīr, Lahore, Shamā Book Agency, 2004. P:340,341
[xxiii] مسلم،الامام، ابی الحسین بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری (204ھ۔261ھ)صحیح مسلم، كِتَاب الزَّكَاةِ،باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ, ، دار السلام للنشر والتوزیح،الریاض، الطبعۃ الثانیۃ، محرم 1421ھ۔اپریل 2000م ، رقم الحدیث: 2290، ص: 410
Muslim, Al-Imām, Abi-īl-Hussaīn Bin Hajāj Bin Muslim Al-Qashīrī Al-Nīsābūrī (204-261AH), Sahīh Muslim, Dārūssalām Lilnashar-wal-Tūzīh, Al-Rīādh, 2nd ed, Moharram 1421AH, April 2000, Kitāb-al-Zakāt, Chapter Ism-e-Mane’zakāt, H#2290, P:410
[xxiv] الاسراء 27،26:17
Sūrah al-isrā, 17:26,27
[xxv] سیّد قطب شہید، تفسیر فی ظلال القرآن (ادارہ منشورات اسلامی، لاہور ج:۴،س۔ن) ص: 392
Syīd Qutab Shahīd, Tafsīr Fī Zīlāl ul-Qur’ān, Idāra Manshūrāt Islāmī, S.N., vol4,P:392
[xxvi] الاسراء29:17
Sūrah al-isrā, 17:29
[xxvii] نسائی، امام، احمد بن شعیب ،سنن النسائی ، کتاب الزکاۃ، بَابُ : الاِخْتِيَالِ فِي الصَّدَقَةِ، رقم الحدیث: 2560، ص: 306
Nisāyī, Al-Imām, Ahmad Bin Shoaib, Sunan Al-Nisāyī, Kitāb-al-Zakāt, Chapter Al-Ikhtīyāl Fī-alSadaqa, H#2560, P:306
[xxviii] الھمزہ ،2،1:104
Sūrah al-humuza, 104:1,2
[xxix] البقرۃ 43:2
Sūrah al-baqarah, 2:43
[xxx] الحدید 11:57
Sūrah al-hadīd, 57:11
[xxxi] البقرۃ 219:2
Sūrah al-baqarah, 2:219
[xxxii] النساء1:4
Sūrah al-nisā, 4:1
[xxxiii] الذاریات 19:51
Sūrah al-zarīyāt, 51:19
[xxxiv] الاسراء70:17
Sūrah al-isrā, 17:70
[xxxv] البقرۃ 274:2
Sūrah al-baqarah 2:274
[xxxvi] الحشر 9:59
Sūrah al-hashr, 59:9
[xxxvii] الاعراف 10:7
Sūrah al-a’rāf, 7:10
[xxxviii] البقرۃ 168:2
Sūrah al-baqarah, 2:168
[xxxix] ابوالاعلیٰ، سیّد مودودی، اسلامی ریاست (پاکستان، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور، 1985ء)ص:618
Syed Mūdūdī, Mawlānā, Abūl āla, Islāmī Rīyāsat, Islamic Publications Ltd Lahore, 1985. P:618
[xl] الاعراف 31:7
Sūrah al-a’rāf, 7:31
[xli] البقرۃ 3:2
Sūrah al-baqarah, 2:3
[xlii] النساء 29:4
Sūrah al-nisā, 4:29
[xliii] النحل 90:16
Sūrah al-nahl, 16:90
[xliv] التوبۃ 71:9
Sūrah al-taūba, 9:71
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |